چالیسواں (1)
رات بارش ہوئی تھی۔
سب دنوں سے زیادہ آج پھول دیر تک سوئی۔ یا بچوں کو ایسا لگا ماں سورہی ہے اور آج اس کی جگہ دونوں لڑکوں میں سے ایک کو کام پر جانا پڑے گا۔ اس نے اٹھ کر بے ضرورت لمبی انگڑائی لی، مُنھ کھول کر جھوٹی جمائی لے رہی تھی کہ کَلی، چھوٹی لڑکی نے ماں سے چپٹتے ہوئے کہا: ’اماں رات بابا آیا تھا۔‘ وہ خوشی سے بے حال تھی۔ کمرے سے ملی ہوئی چھت سے باقی تینوں بھی ماں سے چپٹنے آگئے__ دونوں لڑکے ٹِلّو، چھوٹے اور بڑی بیٹی بوندی۔
پھول نے خوشی کا سا مُنھ بنایا اور انہیں ہٹاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔
کُھلی چھت پر اس کا سُسرا سیلی لکڑیوں کو بانس کی پھونکنی سے پھونک کر چائے بنا رہا تھا۔ اُس نے دھوئیں سے آنکھیں چراتے ہوئے سرگُھما کر پھول کو دیکھا اور مسکرا کر کہا: ’خبر تو نے سن لی؟‘ پھول نے ہاں میں سرہلایا۔ ’تیرا سوامی آیا تھا۔‘
پھول بے دلی سے کھڑی اس کی بات سُن رہی تھی۔ لفظ ’سوامی‘ پر بھی وہ اِس وقت نہیں چونکی، ورنہ ہمیشہ سے پھول سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے لئے ’تیرا آدمی‘ کہتا تھا۔
پھر بولا: ’وہ سکھی ہے۔‘
’ہاں‘ پھول نے بغیر جذبات کے کہا۔
’اس نے دوسرا جنم لیا ہے: پُنر جنم، ہرن کے روپ میں۔‘ پھول کا سرعادتاً ہلا۔ ’تو بھی اس کے پگ کے نشان، نہیں، میرا مطلب چرنوں کے درشن کرلے۔ راکھ ماتھے پر لگالے۔ دِلاسہ ملے گا۔‘‘
’اچھا‘ کہتے ہوئے پھول نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا۔ پیچھے سے اس کے سسر کی آواز آئی: ’ارے کہاں چلی! پہلے اس راکھ کو تو ماتھے لگالے۔‘ آخری بات کہتے ہوئے اُس کی آواز بھرّا گئی۔
نیچے جنگلی اِدھر اُدھر مُنھ مارتے پھررہے تھے، زیادہ وہاں تھے، ذرا فاصلے پر، جہاں بھینسے گاڑیاں مَیلا لاکر پھینکتی تھیں۔ میلے اور کیچڑ میں کچر کچر کی آواز کے ساتھ ان کی تھوتھنیاں چل رہی تھیں۔ پاس ہی سوکھے میں ایک سورٔیا کے بچے اس کے تھنوں سے چپٹے ہوئے تھے اور وہ خود سورہی تھی۔ جس نیم کے درخت کا سایہ اوپر آدھے صحن پر رہتا تھا اس کی ایک شاخ پر پتوں میں چھپا سُندر چڑیوں کی تاک میں بیٹھا تھا۔ پاس کے گھروں سے بھی گیلی لکڑیوں کے جلنے کا نیلا دودھیا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ وہی زندگی تھی جِسے دیکھنے کی وہ عادی تھی۔ لیکن آج اُکتا دینے والی بن گئی تھی۔
سندر سے پہلے اس کی ماں بھی چڑیوں کے شکار کا پاپ کرتی تھی اور پٹتی تھی۔ ایک رات نجانے کتنی دیر اس نے ایک سانپ کو چھت پر گھیرے رکھا تھا اور اندر نہیں آنے دیا جہاں سب سو رہے تھے۔ یہاں تک کہ اُس کے پھنکارے اور اِس کی غُرغُر سے سب جاگ اٹھے اور سانپ بھاگ گیا۔
اُس دن کے بعد وہ سب کو پیاری ہوگئی تھی__ زیادہ کھانے کو ملتا، چڑیاں پکڑنے پر مار پڑنی بند ہوگئی اور صبح سوکر اٹھنے پر اگر پہلے اس پر نظر پڑے تو بچوں کا دادا اُسے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر پرنام کر لیتا۔
ایک دن بوندی نے کہا تھا: ’دادا تم بلّی کو کیوں سلام کرتے ہو؟ وہ کوئی گیّا ہے۔‘
شمبھو نے کہا: ’ہر بلّی کے آگے تو ہاتھ نہیں جوڑتا ہوں۔ ہماری جمنا نے تو ہم سب کی جان بچائی تھی۔ دیوی تھی، اس سے۔‘
سورٔیا کو دیکھ کر پھول کو خیال آیا اس بڑے دن پر شاید یہ بھی کٹ جائے گی اور جانے جب تک کیا کچھ ہوجائے گا۔
ضرورت سے نمٹ کر وہ برابر کے کھنڈر جیسے مکان کے کُھلے برآمدے پر بیٹھ گئی۔ پیچھے بند کمرے کو زنگ کھایا ہوا تالا لگا تھا۔ مکان اس کی یاد سے پہلے کا ویران تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا پہلے اس میں کون لوگ بستے تھے، اور کب وہ اِسے چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید اس کے لوگوں کے یہاں آگر بسنے سے پہلے۔ اس وقت جو چیز اُسے چاہیے تھی وہ تھا تمباکو کا پان۔ لیکن پان بھی تب ملتا اگر وہ کام پر جاتی اور اس گھر میں جہاں جب مِیلا اٹھا چکے تو نالی پر اپنے ہاتھ دھلوا کر وہ پان بیگم صاحب سے لیتی تھی اور اگر چائے کا وقت ہو تو پہلے چائے ملتی تھی__ اس کی پیالی میں، پھر پان۔ پر اُسے لگ رہا تھا آج وہ اتنی تھک گئی ہے کہ کام پر جانا اس کے بس کا نہیں ہے۔ کیوں تھک گئی یہ خود اسے معلوم نہیں تھا۔
آخر یہ سب کیا کِیا تھا بڈھے نے؟ مرنے کے چالیس دن بعد، مسلمانوں کی طرح، آتما کے اپنے گھر لوٹ کر آنے کا کھیل! مجھے خوش کرنے کو؟ بچوں کو خوش کرنے کو؟ یا اپنا دکھ مٹانے کو! کتنی بار وہ کہہ چکا تھا: ’تُو تو بُجھی بجھی رہنے لگی ہے۔ بجھا تو مجھے رہنا چاہیے تھا کہ ہٹا کٹا بیٹا بڈھے باپ کو چھوڑ کر چلتا بنا۔ پر مجھے دیکھ، اب بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہوں، چار چلم روز پیتا ہوں اور مل جائے تو آدھ سیر گڑ بھی بیٹھے بیٹھے ہجم کر جائوں۔‘
کتنا بڑا جھوٹ! خود پھول نے اُسے مُنھ چھپا کر روتے دیکھ تھا۔ اور کل ایکا ایکی کیا سوجھی کہ اس نے پوتوں، پوتریوں کو پاس بلا کر کہا تھا: ’کل متھرا کو گئے پورے چالیس دن ہوں گے‘ حالانکہ کسی نے گھر میں دِنوں کی گنتی نہیں رکھی تھی، نہ جات والوں میں سے کوئی کہنے آیا تھا: شمبھو کل تمہارے بیٹے کا چالیسواں ہے۔ کہو کیا صلاح ہے؟ منائو گے؟ ’آتے دکھ میں ساجھا کرنے کے بہانے کام ہوتا نشے سے!‘ پھول نے سر کو جھٹکا دیا۔
راکھ ماتھے پر لگانے کی بات سن کر بچے دادا کا مُنھ تکنے لگے کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ متھرا کے مرَن سے جس طرح وہ کرتا آیا تھا اس وقت بھی اس نے پھول کے دل کا زخم ہرا کر دیا تھا۔ وہ چپ رہی۔
کلی نے جو دادا کی گود میں جا بیٹھی تھی اس کا مُنھ اپنی طرف کرکے کہا: ’باپو آئے گا کیا دادا؟‘
شمبھو نے کہا: ’ہاں آئے گا۔‘
’کب؟‘ __ ’کس وقت؟‘__ ’آکے پھر چلا تو نہیں جائے گا؟‘__ ’رہنے کو آئے گا نا؟ یا بس ملٹ بھرکو۔‘
’ہیں دادا؟‘ بوندی، چھوٹے اور کلی نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔
ٹِلّو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا: ’کوئی قبر سے ہمیشہ رہنے کو آتا ہے!‘ اور دادا کا دل جلا کر باہر چلا گیا۔
چھوٹے نے کہا: اور کیا؟ آئے اور بس گئے۔ ہماری باری آئے گی تو ہم تم بھی ایسے ہی کریں گے۔‘
بوندی نے کہا: ’اور بِنا کسی سے بات کئے چل دیں گے؟‘
سب نے مرنے کے بعد لوٹ کر آنے والوں کا حال سُن رکھا تھا سِوائے کلی کے۔ اس نے بڑے تینوں کی بات کو پرکھنے کے لئے دادا کی آنکھوں میں جھانکا اور رونے لگی۔
رات سب کے سوجانے کے بعد پھول نے ہلکی چاندنی میں سسرے کو بغیر کیسی بھی آواز نکالے اٹھ کر چھت پر چولہے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ آسمان پر چاند بادلوں سے کھیل رہا ہو گا جو اُسے کبھی پتہ پڑتا بڈھا کیا کر رہا ہے، کبھی نہیں۔ شاید لکڑیوں کو اِدھر اُدھر کررہا تھا۔ پھول نے جان لیا چلم کے لیے کوئلے ڈھونڈ رہا ہے اور جب وہ نیند میں جا رہی تھی تو اُسے بوڑھا جھکا جھکا چل کر کمرے کی طرف آتا نظر آیا تھا۔
اس وقت وہ راکھ کمرے کے دروازے سے ہاتھ دو ہاتھ اندر تک بچھائی ہوئی نظر آرہی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے کُھروں کے نشان تھے۔ بکری کے تھوڑے بڑے بچے کے سے۔ یَا جیسے مٹھی کو بھینچ کر مٹی پر ہلکے سے مارنے سے بنائے جا سکتے ہیں‘ پھول کے خیال میں آیا۔ چھت کی راکھ کو مینھ دھوچکا تھا۔
آس پاس کے گھرانوں کی کام کرنے والیاں کمانے کا سامان سنبھال کر اپنے ٹھکانوں کو جا چکی تھیں۔ جن کے بچے مشن اسکول جاتے تھے وہ وہاں جا چکے تھے لیکن زیادہ تر کے بڑے بچے بھی اپنے ٹھکانوں کو۔ مرد میونسپلٹی کے ملازم تھے۔ انہیں تو جانا پڑتا ہی تھا__ ’نہ جاتے تو پٹتے اور تنکھوا کٹتی سو الگ۔‘
جنہوں نے کام کو زندگی کے لئے ضروری نہیں سمجھا تھا، یا جب مَن کرتا ڈبکی لگا جاتے تھے وہ گھر میں پڑے بھنگ پیتے، بیویوں کی سو سنتے تھے اور اگلے دن کام پر جاتے تو اوپر والوں کی گالیاں۔ سب کی بیویاں انہیں چکنے گھڑے کہتی تھیں۔ رہا کھانے کا تو ایسی بیوی کون ہے جو خود تھورے اور پتی اس کا مُنھ دیکھے۔ سب کو مل ہی جاتا ہے۔
ہرطرف سنّاٹا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت بوڑھا اُسے چائے روٹی کے لیے بلا چکا تھا لیکن وہ کہہ کر آئی تھی: ’تم کھا لو، میں پیچھے کھا لوں گی‘ اور نیچی آواز میں بڑبڑائی: ’جب پیٹ مانگے گا۔‘
بوڑھے نے زیادہ زور بھی نہیں دیا۔
پھول برآمدے کے کھرنجے پر ساری کے آنچل سے چہرہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔
چالیس دن پہلے اُس دن کا سورج نکلا تھا جب اس کے سوامی متھرا کو گاڑھنے لے جایا گیا تھا__ یعنی اگر اس کے سُسرے نے دنوں کا حساب صحیح رکھا تھا__ ڈیڑھ دن درد سے تڑپنے کے بعد۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا کہتے ہیں پھول کی وجہ سے ، نہ وہ گھر آکر کہتی کلبے نے کیا کیا تھا نہ وہ آپے سے باہر ہوکر لڑنے پہنچ جاتا۔ چار بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی پھول خوبصورت عورت تھی، ہوسکتا ہے کچھ کلیاں کِھلنے سے پہلے ٹہنی سے جھڑ گئی ہوں۔ پوسٹ کارڈی رنگ، گوری ہوتی تو بھی ایسی بھا جانے والی نہ ہوتی۔ دونوں کلّوں پر جو سوکھے پتے کی رنگت کے نشان تھے انھوں نے اس مُورت کو اور سجا دیا تھا۔ پہلے کانوں میں چاندی کی بالیاں پہنتی تھی__ اب نہیں۔ کانسی کی چوڑیاں، چاندی کی لونگ، پیر کی انگلیوں کے چھلے سب کو اس دن اس نے اتار پھینکا تھا جب زخمی متھرا کو بجائے ہسپتال لے جانے کے جات والے اٹھا کر گھر لائے تھے۔ موت اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ سارا چہرہ سوجا ہوا، اندر خون کے جم جانے سے پپوٹے نیلے پڑ گئے تھے اور گھر والوں میں سے پتہ نہیں کسی کو پہچان بھی رہا تھا یا نہیں۔ بس پیٹ پکڑے ہائے ہائے کررہا تھا۔ جیسے ساری چوٹ وہاں تھی۔ کبھی خدا کو یاد کرتا تھا، کبھی کہتا ’پرماتما دیا کر‘۔ کبھی دونوں کو بھول کر ہولی فادر، ہولی مدر کو پکارنے لگتا۔
متھرا کو ہسپتال نہ لے جانے کا حکم اس پر اتیا چار کرنے والے نے دیا تھا۔ ’یہ پیسے میں جو کرنا ہے گھر پر کرائو۔ ٹنچر لگائو۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ بَن رہا ہے۔‘
’بن نہیں رہا سرکار‘ ایک جمعدار نے کہا۔ ’آپ نے اس پر جُلَم کیا ہے۔ ہم اسے سرکاری ہسپتال لے کر جائیں گے۔ وہاں علاج مالجا بھی ہوگا اور بھید بھی کھل جائے گا۔‘
’میری رپٹ لکھانے؟ جائو۔ ضرور جائو‘ کلب علی کا سینہ اذان دیتے ہوئے مرغے کا سینہ بن گیا۔ ’تم میں سے ایک ایک کے چوتڑوں میں پِسی لال مرچ بھروا کر سارے دن دھوپ میں کھڑا نہ رکھا تو میں۔۔۔۔‘
اس ادھورے جملے ہی میں سب کی ہوا سرک گئی کیوں کہ ایسا ممکن تھا۔ ٹھیک ہے ضلع کا کلکٹر انگریز تھا، وہ انصاف کرتا، لیکن بیچ میں جو کوتوال، اِنسپٹَرّ، تھانہ منشی اور کانس ٹیبل تھا وہ تو انگریز نہیں تھے۔ وہ وہاں تک انہیں پہنچنے دیتے! پر خود کلکٹر کے بنگلے کے چوکیدار، پہرے دار، مالی کون سے گورے تھے جو صاحب تک پہنچے دیتے!
سب کھڑے کلب علی کو دیکھ رہے تھے۔ کلب علی ٹھیکیدار، جس کی پہنچ بڑے بڑوں تک تھی۔ اس لئے کہ ممبر تھا اور اس سے بڑی یہ بات کہ لکھ پتی تھا۔
کلب علی نے کہا: ’اور ہاں سرکاری ہسپتال میں یہ لکھوانا مت بھولنا کہ اس نے میونسپلٹی کے ممبر سے بدتمیزی کی تھی۔ تو تڑاق پر اتر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا :’ ’سڑک کا کوڑا میرے گھر کے سامنے کیوں پھینک کر جا رہا ہے۔ اٹھا اِسے۔‘‘ اور اس کی موت آئی تھی جو اس نے ایک شریف آدمی سے کہا: ’’خود اٹھا اور کوڑے گھر پھینک کر آ۔‘‘ اس لئے سالو تمھیں تنخواہ ملتی ہے سرکار سے؟‘
سب کا چہرہ لٹک گیا جیسے عدالت میں کھڑے ہوں اور جج نے فیصلہ سنایا ہو۔
ایک نوجوان خاکروب نے سر اٹھا کر کلب علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا: ’پر صاحب یہاں تو تمہارے در دوارے پر جھاڑو دلی ہوئی ہے۔ تنکا تک نظر نہیں آتا۔‘‘
کلب علی نے اس کے چہرے کو یاد رکھنے والی نظر سے دیکھتے ہوئے قہر بھری آواز میں کہا: ’کیا نام ہے تیرا؟‘
’چُپ رہ‘ جمعدار نے کہا۔ ’چَلو چلو اس ملک میں پہلے کسی گریب کی فریاد کی سنوائی ہوئی ہے جو تمہاری ہوگی۔‘
دن ڈھلے اگلی شام متھرا نے دم توڑ دیا۔
(جاری ہے)
- سارے جہاں کا درد - 12/01/2023
- اب کیا فردا کیا دیروز، کیسی آنے والی کل، کیسی گزری ہوئی کل - 16/06/2020
- چالیسواں (3) - 24/02/2018
- چالیسواں (1)
- چالیسواں (2)
- چالیسواں (3)

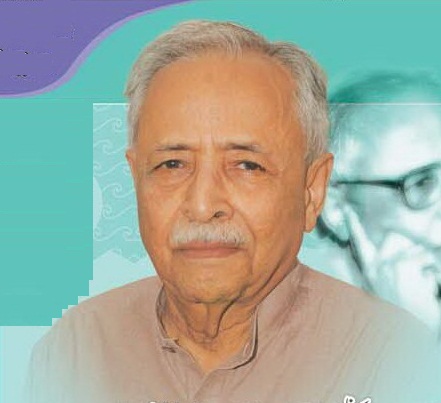

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).