جینا رپون: ابھی سحر کا ذکر ہے روایتوں کے درمیاں

”برسات کے بھی سات سر ہوتے ہیں۔ بسنت کی پھوار۔ ساون کی جھڑی۔ بھادوں کے جھلے۔ ماگھ کی مہاوتیں۔ کاجری کی رم جھم۔ ماہ کی ملہاریں۔ ہائے کیا ہو گیا ہے میری زبان کو؟ اب تو نہ بارش ہوتی ہے نہ مینہ برستا ہے۔ پانی گرتا ہے۔“
جاوید صدیقی کے افسانے، بیگم کا یہ اقتباس اس لمحے بس کی کھڑکی پر ٹپکتی رم جھم سے ذہن کے نہاں خانے سے امڈ آیا۔ برسات کا موسم جوبن پر ہے۔ ہمارے شہروں میں برسات کا ایک خاص احساس پایا جاتا ہے۔ افسردہ کر دینے والی اداسی جو عشق سے زیادہ وجودیت کے بحران سے جڑی ہوتی ہے اور ایک ان مٹ بانجھ سکوت۔ برساتی جھکڑ کسی مداری کے ایسے ایک ٹانگ پر اچھلتے، پل بھر میں اپنا بھگوتا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ صبح کے ساڑھے چھ بجے ہیں۔ لاہور سے ایک بس میں بیٹھا ملتان کی طرف رواں ہونے کو ہوں۔ آج ملتان بک کلب کی روایتی ماہانہ نشست ہونا قرار پائی ہے۔
ملتان۔ اس شہر کا اپنا ایک سکوت ہے جسے برقرار رکھے صدیوں سے وقت کی کوکھ میں انسانوں اور بسوں کو جھیلے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت تھا جب ملتان آنے والوں کو سب سے پہلے حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کے گنبد دکھائی دیتے تھے۔ اب صرف میٹرو بس نظر آتی ہے۔ ملتان کی دو روایتیں میرے لیے بیتے ماضی کے ناسٹلجیا کا وجہ بنتی ہیں۔ ایک شمسی ہندو اور دوسرے حسینی برہمن۔ محمد حسن معراج لکھتے ہیں کہ شاہ شمس کے حسن سلوک سے مسلمان ہونے والے آج بھی اپنے نام کے ساتھ شمسی کی عرفیت لگاتے ہیں۔
تقدیس کی یہ روایت صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، بلکہ تقسیم سے پہلے ملتان کے کئی محلوں میں آپ کے عقیدت مند ہندو بھی رہتے تھے، جو خود کو شمسی ہندو کہلواتے تھے۔ حسینی براہمن پنجاب کے موہیالوں میں سے تھے۔ راہب دت سے اپنا تعلق بتانے والے ان براہمنوں کے چند ایک گھرانے ملتان میں بھی ملتے تھے۔ مذہب سے بے نیاز، اس مکتبۂ فکر کے لوگ حضرت حسین سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔
جیسے ہی اعلان ہوا کہ بس ملتان شہر پہنچ چکی ہے تو خالدہ حسین کے افسانہ ”ہزار پایہ“ کی ابتدائی سطر کے جیسے، ”اندر کے ٹھنڈے اندھیرے کے بعد ، باہر کی چکاچوند اور تپش پر میں حیران ہو گیا۔“ یہ ملتان شہر میں میرا سواگت تھا۔ متعلقہ چائے خانے پہنچ کر کتاب کی بحث چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے شروع ہوتی ہے۔ تین چار لوگ اپنے پسندیدہ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ان پیراگراف پر بحث شروع ہوتی ہے اور یوں ملتانی سرزمین میں اکٹھ کیے بھٹکے بھولے، انفرادی شناختی بحران لیے مرد و زن بحثی لہجہ اختیار کرتے ہیں۔
کسی بھی حق کی جدوجہد سے پہلے کا مرحلہ آگہی کا ہوتا ہے تاکہ جدوجہد کو شعوری اور بامقصد بنایا جاسکے۔ عزم مصمم کا یہ ایک پہلو ہے۔ آج تک کی جتنی بھی جدوجہد و نظریات ناکام ہوئی ہیں ان کے پیچھے کسی سطح پر شعوری بنیادوں کا کھوکھلا ہونا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جینا رپون، برطانوی دماغی امور کی سائنسدان اور خواتین کے حقوق کی پروفیسر، اس مسئلے کو عوامی سطح پر اچھالتی ہیں تاکہ یہ ایک عوامی موضوع کا روپ دھار سکے۔
جینا رپون کتاب کو خالصتاً سائنسی زبان میں لکھنے کی بجائے ”جینڈر اور سیکس“ سے جڑی بے شمار ایسی پرتوں سے پردہ اٹھاتی ہیں جن سے ہمیشہ خواتین کے عوامی کردار کا استحصال کیا جاتا رہا ہے۔ خاص زبان و الفاظ کا چناؤ، سالوں سے چلتے دقیانوسی تصورات جو وقت کی آڑ میں حقائق کا روپ دھار چکے ہوں، تحقیق کا محدود سطح پر ہوتے ہوئے سنجیدہ نتائج مرتب کرنا جس سے خواتین کے طبقہ کو مردوں سے کم تر دکھایا جاتا رہا اور ایسی ہی نیورو سائنس کے استحصالی اور غیر حقیقی نتائج کی بنیاد پر نفسیات کی ایک نئی شاخ کا پنپنا ( جس میں سیلف ہیلپ بکس شامل ہیں۔ راقم کو تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ہمارے مردانہ و ہمہ قسمی کمزوری والے باباؤں کی ملی بھگت تو نہیں ہے جنہوں نے اب دیواروں سے کوچ کر کے صفحوں پر املی رکھ کر بیچنا شروع کر دیا ہے؟ ) ۔
دماغ ایک ٹھوس ترتیب سے کام نہیں کرتا بلکہ بے شمار سماجی و سیاسی پہلو بالواسطہ ذہنی نظام کی تشکیل میں اثرانداز ہوتے ہیں۔ گزشتہ تحقیق میں یہ سمجھا جاتا تھا (ارادتاً ) کہ دماغ صرف ایک مخصوص حیاتیاتی عمل کے تحت کام کرتا ہے اور اس کے مطابق خواتین دماغی معاملات میں مردوں سے کم تر ہوتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ ریاضی اور نقشوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہمیشہ مردوں سے پیچھے رہی ہیں۔ جینا رپون اس من گھڑت قصے کو مردوں کے تعصب سے جوڑتی ہیں۔ سائنسی تحقیق پر چونکہ مرد سائنسدانوں کی اجارہ داری رہی ہے اس لیے وہ حقائق کو مروڑ تروڑ کے پیش کرتے رہے حالانکہ نتائج اس کے برعکس ہوتے تھے۔ اپنے ان دلائل کو جینا جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں حقائق سے وقتاً فوقتاً ثابت کرتی ہیں۔
جینڈر ایکولیٹی پیراڈوکس سے پردہ اٹھاتے ہوئے جینا لکھتی ہیں کہ ایسا نہیں یہ کہ جدید دنیاوی و کاروباری معاملات میں خواتین کو حقوق دیے جا چکے ہیں۔ صورت حال اس کے برعکس دیکھی گئی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں مرد و زن کی برابری کا خلا دوسرے ممالک سے زیادہ پا گیا ہے۔ فن لینڈ، ناروے اور سویڈن کی مثالیں دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ کہیں پر یہ تناسب 20 کا ہے تو کہیں 25 کا۔
بچوں پر کھلونوں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ کیسے اور کون طے کرتا ہے کہ لڑکی کو گڑیا تھمانی چاہیے اور لڑکے کو کسی جنگجو کا اوتار بنانا چاہیے؟ رنگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ برتا گیا۔ یہ کیسے، کب اور کس نے طے کیا کہ لڑکی ہے تو گلابی رنگ پسند کرے گی اور لڑکا ہے تو نیلا رنگ؟ بچے پیدا ہوتے ہی کسی اسفنج کی مانند ہوتے ہیں جنہیں آپ جو دیں گے وہ جذب کریں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے رنگ اور کھلونوں کا انتخاب خود کرنے دیں۔ جینا رپون اس ”پنکفکیشن“ کے بے حد خلاف نظر آتی ہیں۔ وہ اسے بچوں کو ڈربے میں بند کرنے کے مترادف ٹھہراتی ہیں جس سے ان کے عزم و خود ارادی میں نمایاں کمی آتی ہے۔ خود اعتمادی کا مادہ بھی بچپن سے انسان کے ساتھ چلتا ہے۔
کیا یہ صنفی رویہ والدین اپنے بچوں کو سراہتے ہوئے ہوئے بھی اختیار کرتے ہیں؟ کیا لڑکوں سے درست کام کی جب کہ لڑکیوں سے درست اخلاق کی ہی توقع کی جاتی ہے؟ لڑکی اگر تعلیمی بنیادوں پر ناکام ٹھہرتی ہو تو ضرر نہیں، اخلاقی اقدار نہیں چھوڑنے چاہئیں؟ مرد تو چونکہ مرد ہیں تو ان سے اخلاقی برائیوں کی توقع رکھنا ہمارے یہاں معاشرتی مزاج کا حصہ نہیں ہے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جنہیں جینا رپون دہراتی نظر آتی ہیں۔ سماجی سطح پر شناخت کی تشکیل کن پہلوؤں کے زیراثر ہوتی ہے، سمجھنا اشد ضروری ہے۔
ہمیں ان صنفی بنیادوں پر پھیلی معلومات و خبروں کا جائزہ لینا چاہیے جو معاشرتی سطح سے لے کر انٹرنیٹ اور خاندان، احباب، دفاتر و جامعات میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ خبریں اور معلومات ہمارے نظریات و خیالات پر عموماً منفی اثر مرتب کرتی ہیں۔ ان خبروں کا سماجی و سیاسی سطح پر توڑ ڈھونڈنا چاہیے۔ ہینا آرنٹ آزادی سے جڑی ایک تقریر میں کہتی ہیں کہ سیاست کے بغیر کوئی بھی معاشرتی آزادی حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ دوسری سطح پر ایسا معاشرہ جہاں ہمہ جہتی ایسے اعلی اقدار کا ظہور جن میں سے آزاد فضاء جنم لیتی ہے، نہ ہونے پائے تو وہ معاشرہ سیاسی معاشرہ نہیں کہلایا جا سکتا۔
پروفیسر جینا رپون کی یہ کتاب مختلف پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے۔ جس طرح شناخت کے مسئلے کو سائنسی بنیادوں پر اٹھایا گیا ہے منفرد اور فکر انگیز ہے۔ ملتان بک کلب کی بحث میں تنوع کا عنصر اس بک کلب میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ متنوع شخصیات حصہ لیتے ہوئے اپنا اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ مختلف خیالات لیے زندگی کو جھیلتے یہ لوگ کتابی بحث میں مشغول ہو کر لمحہ بھر کو ایک جامعیت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ جب دوپہر سایوں میں ڈھلنے لگی تو بحث کا اختتام ہونے کو آیا۔ نشست کا اختتام مارگریٹ ایٹوڈ کی نظم ”الو کا گیت“ کی ان لائنز پر ہوتا ہے :
”ہم کو بدلہ نہیں درکار
کفارہ ہمارا مقصود نہیں
ہم کو فقط بتلائے کوئی
ہم کہاں کھوئے
ہم کہاں کھوئے ”
- بھیشم ساہنی کا ناول: تمس - 31/08/2021
- خالدہ حسین کا کاغذی گھاٹ - 25/08/2021
- جینا رپون: ابھی سحر کا ذکر ہے روایتوں کے درمیاں - 16/08/2021



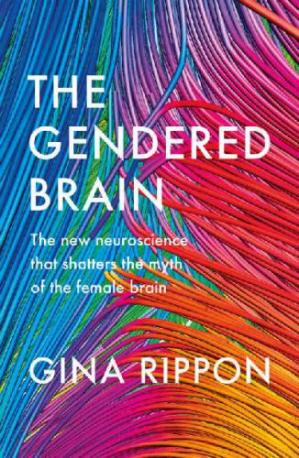
Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).