نیئر مسعود ۔۔۔ کس کو خبر ہے میر سمندر کے پارکی

جب نیئر مسعود کی کہانیوں سے میرا پہلا تعارف ہوا تو وہ وقت ابھی آنے والا تھا جب ان کی کہانیوں میں جادوئی حقیت نگاری کے عناصر ڈھونڈے جاتے، اور ان کو اس تناظر میں عظیم افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا۔ یوں بھی اردو فکشن کے نقاد نت نئی اصطلاحوں سے تبھی واقف ہو پاتے ہیں جب مغرب میں کہیں ان کا چرچا ہو، اس سادہ وقت میں مجھے صرف یہ علم تھا کہ “سیمیا” کے عنوان سے کہانیوں کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے اور بقول سہیل احمد خان، یہ کہانیاں واقعات بیان کرتے ہوئے ماورایت تک جا پہنچتی ہیں۔
میں نے وہ کہانیاں پڑھ لیں اور نیئر مسعود کی کہانی کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔
وقت بیتتا رہا ۔ نیئر مسعود کی تحریریں منظر عام پہ اتی رہیں۔ ان سے ملاقات کا اشتیاق بڑھتا رہا، لیکن سرحد پہ لگی باڑ، ملاقات کے سبھی امکانات کو معدوم کرتی رہی۔ میں نے ان کی کہانیوں میں ان کی شخصیت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ کسی تخلیق کار کی شخصیت کو اس کی تخلیق سے جاننے کی کوشش کرنا ایک گمراہ کن معاملہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ایسا بہت ممکن ہے کہ اگر کبھی خوبی قسمت مجھے لکھنو میں ادبستان کے بڑے دروازے تک لے گئی تو مجھے مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یا شدید غصہ کا۔
اکتوبر 2014ء کی ایک شام، جب میں دہلی سٹیشن سے لکھنو جانے والی گاڑی میں سوار ہوئی۔ اس وقت بھی یہ خیال دامن گیر تھا کہ اگر شخص، افسانہ نگار نیر مسود سے مختلف ہوا تو؟ ایک مرتبہ تو دل چاہا کہ اردہ ترک کر دوں۔ لیکن اس لمحے کے آنے تک ریل گاڑی دہلی سے روانہ ہو چکی تھی، ڈبہ بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور میں پرانی دہلی کے پولیس بھون سے لکھنو جانے کے اجازت نامے پہ مہر لگوا چکی تھی۔ سو اب لوٹ جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ سوچا اب جو ہو، سو ہو۔ اور کچھ نہیں تو حضرت گنج میں رام ایڈوانی سے ملیں گے، ان کی کتابیں دیکھیں گے، اور توفیق ہوئی تو کچھ کتابیں خرید بھی لیں گے۔ نوابوں کے شہر کو چلے ہیں تو لگے ہاتھوں آصف الدولہ کے بنائے بڑے امام بارے کی بھول بھلیوں میں کھو جانے کی کوشش کریں گے، نہ کھو سکے تو چھوٹے امام بارے کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ یہ بھی نہ ہوا تو عبرت پکڑنے کی خاظر گومتی کے کنارے پہ بس کے اجڑ جانے والی دلکشا کوٹھی اور ریزیڈنسی کی دیواروں پہ 1857 کی گولیوں کے نشانات پہ آنسو بہائیں گے، اور پھر مدرا راکشش سے ملنے تو جانا ہی ہے۔
مگر یہ سب خیالات تبھی تک تھے جب تک ارتضیٰ کریم کے توسط سے محسن خان مجھے لینے لکھنو اسٹیشن پہ نہیں پہنچے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد جب انھوں نے کہا کہ کیا پروگرام ہے تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا: نیئر مسعود سے ملنا ہے۔ وہ تو بہت بیمار ہیں، آج ک کسی سے نہیں ملتے، مجھے علم ہے، میں ان کی زیارت کر لوں گی، بی بی جی تو ہیں نا، ان کے ہاتھ کی بنی چائے پی لوں گی۔ اچھا، چلیے کچھ سوچتے ہیں۔ میں ازابیل کو اطلاع دے چکی تھی، ان کا پیغام آ گیا کہ انھوں نے بی بی جی سے بات کر لی ہے۔ ازابیل اور تمثال تو اس وقت امریکہ تھے لیکن انہوں نے بتا دیا کہ میں شام کو نیر مسعود کے ہاں جا سکتی ہوں۔
میری پرانی خواہش پوری ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔
شام ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی جب میں، محسن خان اور شکیل صدیقی ادبستان کے باہری دروازے پہ پہنچے۔ دروازہ بھڑا ہوا تھا مگر اس میں تالہ نہیں تھا۔ محسن خان نے نہایت بے تکلفی سے دروازہ کھولا اور ہم احاطے میں داخل ہوئے۔ گو ازابیل مجھے بتا چکی تھیں کہ ادبستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بطخیں میرا استقبال کریں گی لیکن جس ادبستان کا تصور میرے ذہن مین پختہ ہو چکا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی میناؤں کا خیال تو رہ سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی خونخوار جان پڑنے والی بطخوں کا نہیں جو اپنی بڑی بڑی چونچیں کھولے بھد بھد کرتیں ہماری طرف بھاگی چلی آرہی تھیں ۔ میں سراسیمہ ہوئی لیکن محسن اور شکیل کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آ یا اور وہ بطخوں کے بڑے سے دڑبے نما پنجرے کے سامنے ایک چھوٹے دروازے میں سے گزر گئے۔ یہ نیر مسعود کا گھر تھا ۔ حویلی بدل چکی تھی گو غور کرنے پر پرانا وقت اب بھی دھیان پڑ سکتا تھا۔ عمارت کئی مکانوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک چھوٹی سی راہداری نے ہمیں پہلے بڑے کمرے تک پہنچایا۔ کمرے میں ایک مسہری، دو الماریاں، تپائی اور دیوار کے ساتھ لگے، نیچی پشت والے پرانے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ بی بی جی نے ہمارا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ چند لمحے بیتے ہوں گے کہ اندرونی دروازے کا پٹ کھلا اور ایک لاغر بدن مگر طویل القامت شخص واکر کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ نیئر مسعود تھے۔ مہین سفید بال، چہرے پہ داڑھی کے بال یوں گویا مور کے انڈے ہوں، سفید چکن کا کڑھا ہوا کرتا، مانو گنجفہ کی اماں نے مرنے سے پہلے اہنے ہاتھوں سے کاڑھ کر انہیں پہنایا ہو، سفید پاجامہ۔ گیہواں رنگت، بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے مرجھائی ہوئی لیکن انکھوں میں ایک عجیب کشش۔
ہم ان کے احترام میں نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بی بی جی نےانہیں سہارا دے کر مسہری پہ لٹا دیا، ضعف کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے علم تھا کہ شدید اور طویل بیماری نے ان کی یادداشت پر بھی اثر ڈالا ہے اور سماعت و بصارت پر بھی۔ ان کی بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوچکی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، کچھ پر اسرار قسم کی خاموشی۔
جیسے مسکن کا وہ کونا کہ جس پہ کسی کی نظر نہیں پڑتی مگر وہ ہر گھر میں، ہر کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ بے نام، انجانا، سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی سب کی نظر سے خفیہ لیکن اطمینان بخش۔ میں نے خود کو اسی گوشے میں کھڑا ہوا پایا۔
محسن نے مجھے ان سے متعارف کروایا۔ لاہور کا نام سنتے ہی ان کی انکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی اور کیوں نہ بڑھتی۔ آخر یہ الطاف فاطمہ اور محمد سلیم الرحمان کا شہر تھا۔ بی بی جی ابھی تک خاموش، نیر مسعود کی پائیتی سے لگی بیٹھی تھیں، متوجہ ہوئیں۔ اور کیوں نہ ہوتیں۔ میں صائمہ جو تھی، ان کی لاڈلی کی ہم نام۔
نیئر مسعود کی انکھوں کی چمک اور بی بی جی کی توجہ سے شہ پا کر میں نے نیر صاحب کے قریب بیٹھنے کی اجازت چاہی جو بآسانی مل گئی۔ اب میں نیئر صاھحب کی سرگوشی نما آواز سن سکتی تھی اور ان سے بات چیت کر سکتی تھی۔ ان کی آواز دھیمی تھی مگر آواز کی پچ بتا رہی تھی کہ کبھی وہ متانت بھری گرجدار آواز کے مالک ہوں گے۔ میرے اس خیال کی تصدیق اظہر مسعود نے کی، جو اس محفل میں قدرے دیر سے آئے تھے۔
میری خوش بختی کہ اس روز نیئر صاحب کی طبیعت بہت بشاش تھی۔ لفظ اگرچہ ٹوٹ ٹوٹ کر اور لمبے وقفوں سے ادا ہو رہے تھے، بعضے بعضے جملے بھی ادھورے رہ جاتے لیکن ابلاغ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ گفتگو نہیں کر رہے، کہانی کہ رہے ہیں، اور جان بوجھ کر کچھ خالی جگہیں چھوڑتے جاتے ہیں کہ سننے والا اپنے چشم تصور سے خود ان کو بھر لے۔ میں آج تک ان کی کہانیاں پڑھتی آئی تھی، اب سن رہی تھی۔
ایک سوال جو میں ہر بڑے ادیب سے کرتی ہوں، ان سے بھی کیا۔ اپ کیسے لکھتے ہیں۔ ۔ میرے سوال پہ ان کے لب ذرا سے کھنچے گویا مسکرا رہے ہوں۔ میں اب بھی ایک کہانی لکھ رہا ہوں۔ بڑا کوڑا گھر کی ہاجرہ بیگم کی طرح، انہوں نے گویا خود کو بتایا۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ یہ ملاقات نہیں، کہانی تھی، کہانی کا ایک حصہ تھا۔ اور جیسے ان کی کہانیوں میں موت اچانک در اتی ہے، اس کہانی میں بھی موت در ائی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ اپنے بھید بھرے سینے میں لیے وہ کربلا منشی فضل حسین کربلا میں جا سوئے ہیں۔
فرانز کافکا نے لکھا تھا
If I shall exist eternally, how shall I exist tomorrow?
- نیئر مسعود: کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی - 23/02/2024
- گہر ہائے رفتگاں سے قلمی دشمنی - 23/01/2022
- نیئر مسعود ۔۔۔ کس کو خبر ہے میر سمندر کے پارکی - 06/08/2017



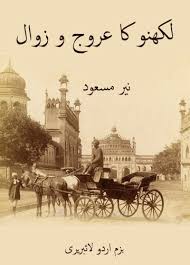

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).