بیچ کا آدمی
وہ مجھے چکلالہ ایئرپورٹ پر ملا تھا۔
بہت دنوں بعد اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، میں بچپن سے اسے جانتا تھا، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں زیرتعلیم رہے تھے۔ پرائمری، سیکنڈری اسکول تک ایک کلاس میں ساتھ ہی رہے۔ اسکول کے بعد میں ڈی جے سائنس کالج میں داخل ہوکر پری میڈیکل پڑھنے چلا گیا جہاں سے مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ آسانی سے مل گیا تھا۔ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد میں ہڈیوں کی بیماری کا ماہر بننے کے لئے انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ سے واپس آکر میں ایک رفاہی ادارے سے وابستہ ہوکر ان کے ہسپتال میں کام کررہا تھا۔
پہلے میں نے سرکاری ملازمت ہی کی تھی۔ میرا تقرر لاڑکانہ کے چانڈکا میڈیکل کالج میں ہوا، وہاں میں کام نہیں کر سکا بڑی مشکل سے ٹرانسفرکرا کے کراچی کے سول ہسپتال میں آیا تو یہاں کام کرنے کا انداز میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں خاموشی سے سرکاری نوکری چھوڑ کر اس رفاہی ادارے سے منسلک ہوگیا تھا۔ اس کے علاوہ میرا پرائیویٹ کام بھی اچھا چل نکلا تھا اور کافی آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میڈیکل کے پروفیشن میں شروع کے چند سال ہی مسائل ہوتے ہیں لیکن ایک بار کام آ جائے تو پھر نہ کام کی کمی ہے اور نہ ہی روپوں کی۔ یہاں تک کہ اگر ایمانداری سے بھی کام کیا جائے تو عزت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
رفیق نے بھی میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کی مگر اس کے بعد ہمارے راستے جدا ہوگئے۔ وہ کامرس میں ڈگری کا امتحان پاس کرکے اپنے ہی خاندان کے کاروبار میں لگ گیا۔ ان لوگوں کا بڑا کاروبار تھا جو روزبروز ترقی ہی کر رہا تھا وہ لوگ شہر کے ہی نہیں ملک کے بڑے لوگ تھے۔ ہماری کبھی بھی دوستی نہیں رہی۔ اسکول سے کالج تک ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے رہے، مجھے نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ہمیشہ اُلجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس سے دوستی بڑھانے کی کوشش نہیں کی، شاید اس کی وجہ میرا اس سے جھگڑا تھا۔
رفیق سے میرا پہلا جھگڑا اس دن ہوا جب چوتھی کلاس میں اس نے مجھے اپنا پنسل کٹر دینے سے انکار کردیا تھا۔ اس وقت لکھتے لکھتے میری پنسل ٹوٹ گئی تھی اور میرے پاس کٹر نہیں تھا۔ میں نے جب اس سے کٹر مانگا تو نہ صرف یہ کہ اس نے مجھے کٹر نہیں دیا تھا بلکہ بڑے غصے سے کہا تھا کہ اپنا سامان خود لایا کرو۔ اس دن میں نے تقریباً روتے ہوئے ٹیچر سے شکایت کی کہ رفیق مجھے کٹر نہیں دے رہا ہے۔
ٹیچر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہیں ابھی کٹر دیتی ہوں اور پھر انہوں نے اپنی دراز سے کٹر نکال کر مجھے دیا۔ ”رفیق اپنا بخار کسی کو نہ دے، تمہیں اپنا کٹر کہاں دے گا۔ “ انہوں نے ہنستے ہوئے کچھ عجیب لہجے میں کہا تھا۔ میں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی کوئی چیز اس سے نہ مانگی اور کبھی بھی اپنے پاس سے کوئی چیز کسی کو دینے سے انکار نہیں کیا۔
عجیب قسم کے تعلقات تھے ہمارے درمیان۔ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی خرابیوں، ناکامیوں اور مایوسیوں کا حساب رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اسکول کا ساتھ طویل ہوتا ہے اور اس طویل ساتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اسکول کے زمانے کا تجربہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ ذہن کے کسی گوشے میں چھپا رہتا ہے اور یکایک ایک دن یاد آتا ہے کہ ارے یہ تو پہلے بھی ہوچکا ہے۔ اچھا یا بُرا۔
شمالی علاقوں میں زلزلہ آنے کے بعد پہلے دن ہی میں کچھ دوسرے ڈاکٹروں اور رضاکاروں کے ساتھ ایبٹ آباد روانہ ہو گیا تھا۔ ایبٹ آباد سے ہم لوگ مانسہرہ ہوتے ہوئے مظفرآباد پہنچ گئے تھے۔ پنڈی سے مظفر آباد تک لوگوں کا عجیب حال تھا۔ زلزلے کے اوائل دنوں میں ہر شخص سکتے کی حالت میں تھا، انجانا خوف، موت سے قربت کا احساس، ہر شخص ایماندار سا ہو گیا تھا۔
مظفرآباد کا بُرا حال تھا۔ شہر کے اندر ساٹھ ستّر فیصد سے زیادہ عمارتیں زمیں بوس ہوگئی تھیں۔ کوئی عمارت محفوظ نہیں تھی۔ بچے اسکول میں، عورتیں گھروں میں، مرد اپنے دفتروں اور ڈاکٹر نرسیں مریضوں کے ساتھ دیواروں چھتوں کے نیچے زندہ دفن ہوگئے تھے۔ ایسی تباہی و بربادی میں نے شاید فلموں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ عمارتیں گرگئی تھیں، پہاڑ پھسل کر زمین پر گرے تھے، دریا ندی نالوں نے راستے بدل لئے تھے۔
مظفرآباد کا میدان میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا۔ سینکڑوں انسان میدان میں زخمی پڑے ہوئے تھے اور ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرسکتے تھے سوائے اس کے کہ زخمیوں کے زخموں کو صاف کریں، انہیں درد اور انفیکشن کے خلاف دوائیں دیں اور انتظار کریں کہ یہ سارے لوگ مریں نہیں، اس وقت تک جب تک کہ ہسپتال دوبارہ کام شروع کریں۔ تھیٹر میں کام شروع ہوجائے۔ پلاسٹر لگنے لگیں، مریضوں کو بے ہوش کیا جا سکے، آپریشن کر کے ان کے زخم، جسم و جان سے مواد مٹی نکالا جا سکے، ہڈیوں کو جوڑا جائے۔
انسانوں کو اتنا مجبور، لاچار اور مایوس میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ صبح سے شام تک لوگ اپنے اپنے گرے ہوئے گھر کے سامنے بین کر رہے ہوتے تھے۔ خوش قسمت تھے وہ گھر جن کا کوئی نہیں بچا تھا۔ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ لوگ سڑک کے کنارے ویران بیٹھے ہوئے نہ زبان سے کچھ کہتے اور نہ ہی آواز سے روتے، صرف اور صرف آنسوؤں کی لڑیاں تھیں جن سے اُن کا چہرہ تَر رہتا۔ زخمی ہاتھوں سے ٹھیکے داروں کے بنائے مکانوں کے ہوئے ملبے کو اٹھانے کی کوشش ہی کرتے رہنا شاید کام بن گیا تھا ان کا۔ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے ان لمحوں کا جن میں گھر کے مرد بے قراری سے ملبے کے گرد چکراتے رہے، جہاں سے ان کے گھر والوں کے چیخنے کی صدا آہستہ آہستہ موت سے ہمکنار ہوگئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کرسکتے تھے وہ کچھ نہیں کرسکے، صرف اوپر دیکھتے تھے اور جسم کے ہر ایک اَنگ سے روتے تھے۔
تین دن میں ہمارا تھیٹر اور کیمپ ہسپتال بن گیا اور اس قدر کام تھا کہ وقت کے گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے علاوہ اور بھی کئی ٹیمیں علاقے میں آگئی تھیں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، امریکہ، برطانیہ اور روسی ٹیموں کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر کہیں کیوبا اور کہاں یوکرین۔ ان کی خدمت کا جذبہ، ان کے کام کا انداز، نہ کوئی لالچ اور نہ ہی کسی معاوضے کا انتظار۔ عجیب و غریب لوگ تھے وہ لوگ بھی۔ ہر کوئی اپنے سامان، آلات، دواؤں کے ساتھ تندہی سے کام میں مصروف تھا۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد اتنے زیادہ لوگوں کا موبائلائز ہونا بھی میں نے پہلی ہی دفعہ دیکھا تھا۔
دسویں دن مجھے کراچی جانا پڑ گیا۔ کچھ سامان کی اشد ضرورت تھی اور کچھ لوگوں سے امداد کے سلسلے میں ملنا بھی تھا مجھے۔ ایک دوست نے ہی انتظام کر دیا تھا کہ کراچی آنے کے دوسرے دن ہی ایئرفورس کے جہاز میں سامان لاد کر چکلالہ ایئرپورٹ پر سامان لے کر پہنچ جاؤں۔
چکلالہ ایئرپورٹ پر ہی میری ملاقات رفیق سے ہو گئی تھی۔ وہ کسی فوجی جنرل کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، ہم دونوں نے ہاتھ ملایا، حالات پوچھے۔ وہ ایبٹ آباد جا رہا تھا اس سے زیادہ بات نہیں ہوسکی تھی۔ میں اپنا سامان ٹرک میں لاد کر اسی وقت مظفرآباد کے لئے روانہ ہوگیا تھا۔ مظفرآباد کا راستہ کھل چکا تھا اور کافی لوگ آجا رہے تھے۔ زلزلوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا جس کی وجہ سے سراسیمگی کا عالم تھا، لوگ خوفزدہ تھے اور گھروں کے باہر کھلی جگہوں میں رہ رہے تھے۔ حالات میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔
زلزلہ تو ایک بہانہ تھا، ہزاروں سال کی غربت ایک زلزلے کی امداد سے تو ختم نہیں ہوسکتی۔ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے گھر جو خالی تھے وہ گر گئے تھے۔ مرد اور عورتیں جو پہلے ہی بہت کمزور تھے اب مر گئے تھے یا زخمی ہوگئے تھے۔ ان کے بچے جن کی نشوونما میں کمی تھی سڑکوں پر کھڑے امدادی سامان جمع کرنے میں لگ گئے تھے۔ خالی گھر، خالی جیب، غربت، مجبوری، ننگے پاؤں، ننگے جسم، ان سب سے تو نمٹا جاسکتا تھا مگر ذہنی افلاس کی بعض شکلیں دیکھ کر تو میں پریشان ہوگیا تھا۔ مجھے یقین ہوگیا تھا کہ دنیا بھر کی امداد کے باوجود ذہن کا افلاس ختم نہیں ہوسکے گا۔ وہ ذہن کا افلاس جس کے ختم کرنے کے لئے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تعلیم جو دماغ کو روشن کرتی ہے۔ زندہ رہنے کے مقصد کا تعین کرتی ہے۔ یہاں تو جاہل لوگ تھے، روایتوں کے غلام اور اپنے آپ کے قیدی۔
اسی افراتفری کے عالم میں مظفرآباد کے خالی گھروں میں ڈاکے پڑے اور چوریاں بھی ہوئیں۔ رات کے سناٹے میں لوگوں نے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے وہیل اُتار لئے، شیشے توڑ کر کیسٹ اور ریڈیو نکال لے گئے۔ جب کچھ بھی نہ مل سکا تو سیٹیں اُتار کر لے گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاشی طور پر غریب لوگ ذہنی طور پر بھی اتنے غریب ہوں گے۔ ٹرکوں کے پیچھے امدادی سامان کے لئے بھاگتے ہوئے لوگ، گاڑیوں میں آئی ہوئی بیگمات سے بھیک مانگتے ہوئے فقیر۔
میں سوچتا تھا کہ مذہبی تعلیم اور مذہب سے وابستہ لوگ بھی اتنے کمتر ہوجائیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ مذہب انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، انہیں اس قابل کرتا ہے کہ وہ حالات سے مقابلہ کرسکیں کیونکہ مذہب کی تو ابتدا ہی یقین سے ہوتی ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے ایک ایسی ذات پر یقین جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جو صبح کرتا ہے شام کرتا ہے۔ جو جان لیتا ہے، تو زندگی بھی دیتا ہے۔ اس ذات پر یقین کے باوجود انسانوں کا اتنا حقیر ہوجانا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔
مجھے اچھا لگنے نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا کا نظام تو شاید ایسے ہی چل رہا ہے، شاید ایسے ہی چلتا رہے گا، انسانوں کا روگ نہ سمجھ میں آنے آنے والا ہے پیمبر اوتار فلسفہ فلاسفر کچھ بھی تو نہیں بدل سکا اب تو ایسا لگتا ہے کہ نہ تو دنیا میں پہلے کوئی تبدیلی آئی تھی اور اور نہ ہی اب آئے گی۔ میں نے یہی سوچ کر خود کو تسلی دے لی تھی۔
میری رفیق سے دوسری ملاقات مظفرآباد میں ہی ہوئی۔ وہ مجھے عباس میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں ملا تھا۔ میں آپریشن کے بعد دو مریضوں کو عباس انسٹی ٹیوٹ کے باہر بنے ہوئے ایدھی کے میڈیکل کیمپ میں چھوڑنے آیا تھا۔ میں وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ رفیق دو عربوں کے ساتھ انسٹی ٹیوٹ سے باہر آرہا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر وہ رُکا نہیں۔ میرے سامنے ہی لمبی لمبی چار گاڑیوں کے کارواں میں بیٹھ کر شاید وہ لوگ پنڈی کی جانب واپس چلے گئے تھے۔
مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ عربی شیخ عباس انسٹی ٹیوٹ کے لئے الٹراساؤنڈ مشین، ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین اور لیبارٹری کا سامان دینے آئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابھی اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سی ٹی اسکین کا کیا ہوگا اور ہائی کلاس لیبارٹریز کا کیا کام ہے۔ ابھی تک عباس انسٹی ٹیوٹ کے اندر اور باہر لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس چادر، کمبل، لحاف اور کفن تو ہے مگر بستر نہیں ہے۔ جو ٹھنڈک میں پڑے ہیں، ان کے پاس ہیٹر نہیں ہے۔ سلیپنگ بیگ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ جس ملک میں عام حالات میں لوگ لیبارٹری نہیں چلا سکتے وہ اس ایمرجنسی کی صورت میں کیا چلائیں گے۔ جہاں نرس مہیا نہیں، وہاں سی ٹی اسکین کے ٹیکنیشن کہاں سے آئیں گے۔ میرے پاس سوچنے کے لئے بہت کچھ تھا، سوالات بے شمار تھے مگر ان سب باتوں کا جواب کچھ بھی نہیں ملا مجھے۔
مزید پڑھنے کے لیے اگلا صفحہ کا بٹن دبائیں
- گھمنڈی - 05/01/2024
- تم جیو ہزاروں سال - 25/12/2023
- ایک انگوٹھی - 21/12/2023

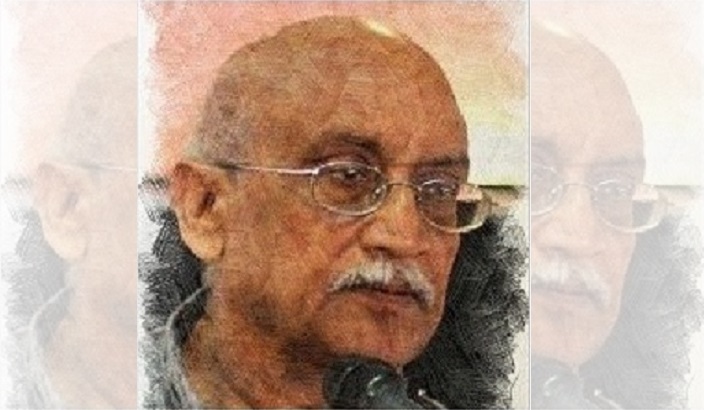

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).