آگرے کے ماسٹر صاحب
گھر میں احمد کا داخلہ اس دن سے بند ہو گیا تھا جس دن اس نے لوگوں کوجمع کر کے بھڑکایا اور پنجابیوں کے گھر میں آگ لگوائی تھی۔ ماسٹرصاحب تو بہت سیدھے آدمی تھے نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں۔ لانبا سا قد دبلے پتلے انسان۔ اردو ایسے بولتے تھے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ ہرجملہ صاف، بغیر کسی غلطی کے۔
وہ آگرے سے آئے تھے۔ جب اپنے لٹے پٹے خاندان کے ساتھ کراچی پہنچے تھے تو صرف دس جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں انہوں نے۔
جیسے ہی آگرے میں ہندو مسلم فساد ہوئے ان کے خاندان والوں نے پاکستان آنے کی تیاری شروع کردی۔ ایک رات بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ خوب مارا کاٹی ہوئی تھی۔ پولیس اور فوج کے آتے آتے وہ اپنے ابا جان کو گنواچکے تھے۔ شروع میں تو بہن کا کچھ پتا ہی نہیں لگا۔ جب چچا نے باپ کی کٹی ہوئی لاش کوچادر سے ڈھانپ دیا اور سلمیٰ کی تلاش شروع ہوئی، تب سب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے بلوائی اٹھا کر لے گئے۔ انہیں ابھی تک یاد تھا کہ امی جان پر کیسا غم پڑا تھا۔
وہ رو رو کر دعا کرتی رہی تھیں کہ ”ا اللہ، مولا رسول ﷺ کے واسطے، انبیا کے واسطے، سلمیٰ کی جان لے لینا، کسی کے ہاتھوں مروادینا مگرکسی ہندو گھر میں نوکرانی بن کر یا رکھیل ہو کر نہ رکھوانا۔“ ابا جی کو دفنانے کے چند ہی دن بعد جب پاکستان جانے کو قافلہ تیار تھا تو چچا جان کے دوست رام لعل کے ساتھ سلمیٰ بھی آئی تھی۔ ساتھ میں پولیس تھی اور فوج کے ہرکارے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔
اس نے بتایا تھا کہ جب بلوائی اسے لے کر بھاگ رہے تھے تو رام لعل نے دیکھ لیا تھا، پہچان لیا تھا اور تھوڑی سی جھڑپ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنے گھر لے گئے تھے۔ بڑی خاطر کی تھی۔ رات باپ، ماں اوربیٹے نے حفاظت کی تھی۔
ہندو محلہ تھا، رام لعل پر بہت زور ڈالا گیا تھا کہ مسلمان لڑکی بلوائیوں کے حوالے کرو مگر رام لعل نے سمجھادیا تھا کہ گھر میں ویسے بھی نوکرانی کی ضرورت ہے۔ اسے نوکرانی بنا کر رکھ لیں گے۔
کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یکایک ہوا کیا ہے۔ ابھی تو سب ٹھیک تھا۔ تاج محل کے سائے میں ہندو مسلمان سب اکٹھے کھیلتے تھے، لڑتے تھے اوراکٹھے رہتے تھے۔ مسلمان پاکستان مانگ ضرور رہے تھے مگرکسی نے بھی نہیں کہا تھا آگرہ اور تاج محل چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں گے۔ پاکستان بن جائے گا، جہاں بنے گا وہاں قائداعظم کی حکومت ہوگی اور وہاں کے مسلمان چین سے رہیں گے۔ وہاں پر ہندو بھی رہیں گے مگرملک اسلام کا ہوگا۔ جہاں ہندو ہوں گے وہاں گاندھی اور نہرو کی حکومت ہوگی اورمسلمان بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے رہ رہے ہیں۔ اور ابھی سے تھوڑی رہ رہے ہیں، سالوں مہینوں کا تھوڑا ہی ساتھ ہے، صدیوں کا ساتھ ہے۔ خاندانوں کی ایک دوسرے سے کئی کئی سالوں کی شناسائی ہے۔
یہ ساری بحث تو روز ہوتی تھی اور روز ہی سب پیٹھا، دال موٹھ کھا کر اور چائے پی کر سوجایا کرتے تھے۔ نہ کسی نے سوچا تھا نہ ہی کسی نے تیاری کی تھی کہ پاکستان جانا پڑے گا۔ اپنی گلیاں، محلے، اپنے گھر، مکان، دالان، دریچے، آگرہ، تاج محل سب کچھ چھوڑ کر ایک مسافر کی طرح بن ہارے ہوئے بھگوڑوں کی طرح سرجھکا کر، شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔
ان کی عمر اس وقت سترہ یا اٹھارہ سال تھی اورانہیں سب کچھ یاد تھا، ذرا ذرا اوربال بال۔ سلمیٰ کو امی نے گلے سے لگایا تھا اور رام لعل کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کی تھی۔ آنکھوں میں گنگا جمنا کی وہ برسات انہوں نے پھر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔
رام لعل نے بہت سمجھایا تھا مگر چچا جان اور برادری فیصلہ کرچکی تھی کہ اب یہاں نہیں رہنا ہے۔ انہیں یاد تھا کہ رام لعل نے چچا جان سے کہا تھا ”توفیق، وقت بدل جائے گا ایک دفعہ گورے چلے جائیں گے اور ان سیاست دانوں کو حکومت مل جائے گی تو پھر یہ لوگ حکومت میں لگ جائیں گے، جیسے گوروں کی حکومت رہی ہے، ویسے ہی ان کی حکومت ہوگی، کیوں جاتے ہو اپنے دروازوں کوچھوڑ کر اور رشتوں کو توڑ کر۔“ وہ سب کو اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔
راستے بھر سمجھاتا رہا، معافی مانگتا رہا مگر چچا ابو نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد اب ان کا دل آگرے سے اٹھ گیا تھا۔ چاندنی رات کا چاند، تاج محل کی اجلی، چمک دار، بلند وبالا، پرکشش، مغرور عمارت کی محبت، آگرہ کی گلیوں کی مٹی، دریا کا کنارا، مائی کی منڈی، سوئی کا گٹڑہ، ہسپتال روڈ، نمک کی منڈی، کشمیر بازار اور ڈولی کہار ان سب سے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ وہ اٹل فیصلہ کرچکے تھے۔ دوستوں کی محبت اور جگہوں کا حسن کچھ بھی انہیں روک نہیں سکا تھا۔
کراچی پہنچ کر ان لوگوں نے آگرہ تاج کالونی میں اپنی جھگیاں ڈال لی تھیں۔ ٹینری روڈ اور مسان روڈ کے درمیان بہار کالونی بھی تھی اوربہار سے آئے ہوئے بہاری مسان کا ٹھکانہ بن گئی تھی۔ مسان روڈ اور ماری پور روڈ کے درمیان آگرہ تاج کالونی بنادی گئی تھی۔ دونوں کالونیوں کے ساتھ ساتھ لیاری ندی بہتی تھی۔
چچا جان نے دو جھگیوں میں گھر بنایا تھا۔ ایک دروازے کے ساتھ دو حصے، ایک میں چچا جان، چچی جان، نصیر، شائستہ، احسن اور مجید تھے اور دوسرے میں ان کی امی، سلمیٰ اور رضوان کا گھر بنا تھا۔ ان کے چچا بھی ان کی ہی طرح شریف تھے۔ نہ کوئی جھوٹا کلیم کیا اور نہ کسی ہندو کے مکان دکان مندر پر قبضہ۔ ساتھ میں آنے والے جو ان لوگوں ہی کی طرح کے لوگ تھے انہوں نے کلیم کر کے بڑی بڑی جائیدادیں حاصل کر لیں۔ کوئی زمین دار بن کر حیدرآباد، نواب شاہ، ٹھٹھہ اور ٹنڈومحمد خان چلا گیا اورکسی نے کراچی میں ہی ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی دکانوں پر قبضہ جما کر کام شروع کر دیا۔
ان لوگوں سے بھی بہت سوں نے کہا مگر جو پشتینی شریف تھے، جن کے خاندان میں کسی نے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا، وہ جعلی کلیم کیسے داخل کر سکتے تھے۔ ان کے چچا جان کو اس بات کا بڑا مان تھا۔ مرتے دم تک وہ فخریہ کہتے تھے میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تکلیفیں اٹھائیں، بھیک نہیں مانگی اوربھائی جو مجھے اولاد سے بھی پیارا تھا اس کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ ساتھ کے لوگوں نے اگر جھوٹ بول کر محل بنالیے ہیں تو کیا ہے، میرا دل صاف ہے اورمیرا خدا میرے ساتھ ہے۔
ان لوگوں نے بڑی محنت کی تھی۔ سارا خاندان کام پر لگ گیا تھا، انہوں نے میٹرک اور آئی اے پاس کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ چچا جان کولی مارکیٹ میں ایک چائے کی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ چچا جان کے بڑے بیٹے نے بھی نوکری شروع کردی۔ آنے کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی نصیر کی شادی سلمیٰ سے ہو گئی تھی۔ یہی ان کے مرحوم ابو کی خواہش تھی اور نہ جانے چچا جان کو اس خواہش کوپورا کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی۔
پاکستان کیسے چل رہا تھا اس کا اندازہ تو کسی کو نہیں تھا، ان کے چچا کوسیاست سے دلچسپی تھی مگر اتنی ہی کہ روز آل انڈیا ریڈیو اور بی بی سی کی خبریں سن کر اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ وقت گزررہا تھا اور وقت کے ساتھ عمریں بڑھ رہی تھیں۔ پھر ایک دن چچا جان اوران کی امی نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی شادی شائستہ سے کردی جائے۔ یہ ایوب خان کے فوجی انقلاب سے پہلے کی بات ہے۔
وہ اور شائستہ بھی دل سے یہی چاہتے تھے۔ بچپن ساتھ کھیل کر گزارا تھا۔ دل ہی دل میں ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کون کون سے جذبات لے کر گھوم رہے تھے۔ سارا خاندان ہی خوش تھا، خاندان کی ایک اورشادی پر۔
شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ایک حادثہ ہو گیا۔ ان کے چچا جان اچھے بھلے گھر لوٹے تھے کہ سخت جاڑے کے بعد بخار چڑھا۔ سول ہسپتال جا کر دکھایا بھی تھا مگر نہ جانے کیا ہوا کہ تین دن میں ہی انہوں نے دم توڑدیا۔ یہ غم سب پر بھاری تھا۔ وہ توخاندان کے اور برادری کے سب کچھ تھے۔ ابھی اس غم سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ نصیر کے بڑے بیٹے کو کتے نے کاٹ لیا۔ گھر میں تو کسی کوپتا بھی نہیں چلا تھا۔ وہ محلے کا آوارہ کتا تھا اور بچہ باہر کھیل رہا تھا کہ وہ کاٹ کربھاگ گیا تھا۔ گھر میں ہی زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کردی گئی تھی مگر تھوڑے دنوں بعد اس پر دورے پڑنے لگے تھے اور وہ چیختا چلاتا ہوا ماں، باپ، دادی، نانی کو بلکتا ہوا چھوڑ کر مرگیا۔
ان کی ماں اوران کی چچی دونوں کے لیے یہ زخم بہت گہرا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ انسان اتنا بے وقعت ہے کہ ایک کتا اس کی جان لے لے۔ ملیریا کا مچھر تمام رشتے ناتوں کے درمیان آ کر باپ، ماں، بھائی، چچا، بیوی بچے چھین لے۔ زندگی اتنی سستی ہے۔ شاید غریبوں کی زندگی اتنی سستی ہے اس کا اندازہ انہیں پاکستان میں اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ سرحد کے دونوں طرف ہزاروں، لاکھوں لوگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا تھا کہ نئے ملک میں غریبوں کی تو عزت ہوگی، انہیں تو کوئی مقام ملے گا مگریہ سب ہی کچھ جھوٹ نکلا تھا۔
غریب، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ امیر کو نہ جانے کیا کچھ مزید اور مزید تر ملتا جا رہا تھا۔ عزت، ایمانداری، شرافت، محنت، دیانت، عظمت کے یہ سارے الفاظ کتابوں میں دھندلاتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی نظر کے سامنے ہندوستان سے آئے ہوئے گنواروں اوربدمعاشوں نے بہت کچھ جعلی طریقوں اورکلیموں سے حاصل کر لیا تھا اورپڑے لکھے سمجھ دار لوگ جوتیاں چٹخارہے تھے۔
پھر حکومت نے لیاری ندی میں سیلاب کے بعد آگرہ تاج کالونی کو توڑنے کا فیصلہ کیا تھا، بلڈوزروں نے مکان گرانے شروع کیے تھے اورکھوکھرا پار کالونی، سعودآباد اور ڈرگ کالونی کے اسی اسی گز کے پلاٹوں میں خاندانوں کو پہنچادیا گیا تھا۔
وہ لوگ شاہ فیصل کالونی آ گئے تھے۔ یہ جگہ انہیں آگرہ تاج کالونی سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ نہ سمندر کی سیلن تھی، نہ لیاری کی بدبو، ایک ایک کمرے کے مکان تھے، لمبی لمبی گلیاں تھیں اور مکان کے درمیان میں گندی گلی، گلی کے نکڑ پر نل تھا جس میں پانی بھی خوب آتا تھا۔ شروع میں بجلی نہیں تھی مگر تھوڑے دنوں میں ہی لوگوں کوکنکشن ملنے شروع ہو گئے۔ آبادی کے چاروں طرف کھلے میدان تھے۔ لیاری کی طرح شہر سے قریب نہیں تھے مگر آہستہ آہستہ ڈرگ کالونی میں ہی سب کچھ بنتا چلا گیا تھا۔
تھوڑے دنوں تو وہ شہر جاتے رہے مگر بعد میں ان کو بھی ڈرگ کالونی کے گورنمنٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ ڈرگ کالونی میں ہی احمد بھی پیدا ہوا تھا، ان کی اور شائستہ کی پہلی اولاد۔ پھر یکے بعد دیگرے چھ بچے ہوئے، پانچ لڑکیاں اورایک لڑکا احمد۔ اسی طرح سے ڈرگ کالونی کی آبادی بھی بڑھتی رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے اسکول میں پڑھاتے رہے تھے، اپنے حالات میں مگن، صابر و شاکر۔ نصیر کا ایک چھوٹا بھائی سعودی عرب میں تھا اور دوسرا بھائی ابوظہبی میں رہ رہا تھا۔
ان کے چھوٹے بھائی رضوان کا داخلہ این ای ڈی میں تو نہیں ہوسکا تھا مگر اس نے گورنمنٹ پولی ٹیکنک سے ڈپلومہ لیا تھا جس کے بعد وہ بھی سعودی عرب چلا گیا تھا۔ پھر یکایک اس کا خط امریکا سے آیا تھا جہاں وہ کسی اسٹیٹ کیرولینا میں رہ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی خط یا کوئی تصویر آجاتی تھی۔ اس نے امریکا میں کسی لڑکی سے شادی کرلی تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ خود بھی پڑھارہے تھے وہاں بچے بھی پڑھ رہے تھے۔ زندگی کے گزرنے کا احساس کسی کو نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا رہتا ہے، اپنی رفتار کے ساتھ جس میں سوئی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے نہ گھنٹوں کا دن بننا اور دنوں کا ہفتہ ہونا اور ہفتوں کا مہینوں اورسال میں ڈھل جانا، عید، بقرعید، آزادی کا دن سب گزرجاتے ہیں، انسان اس وقت چونکتا ہے جب دھماکا ہوتا ہے۔ وہ بھی نہیں چونکے تھے جب احمد نے میٹرک پاس کیا تھا، اسکول میں پڑھنے والا تو میٹرک پاس کرتا ہی ہے۔
اس وقت بھی انہیں کچھ احساس نہیں ہوا تھا جب اس نے بی ایس سی کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا اگر انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں ہوگا تو یونیورسٹی میں داخلہ مل ہی جائے گا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ انجینئرنگ کالج میں داخلے دوسرے طریقے سے بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو محنت کر رہے تھے۔ دن رات اسکول میں، اس کے بعد ٹیوشن، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا تھا، ایمانداری، محنت اور محبت۔
انہیں تو وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا تھا جب احمد کو ایم ایس سی کرنے کے باوجود نوکری نہیں ملی۔ نہ پی آئی اے میں، نہ ہی کے ڈی اے میں، جس جگہ انٹرویو دیا تھا ناکام ہو گیا۔ جہاں کام کرنے کی کوشش کی تھی وہاں سے جواب مل گیا تھا۔ جہاں نوکری ملی وہاں احمد کو کام کرنے کا شوق نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دھماکے کو محسوس کیا تھا، اس دھماکے کو جس میں ایک نیا احمد دھیرے دھیرے، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ غصے سے بھرا ہوا، جس کے معصوم چہرے پر پتلی پتلی نفرت کی لکیریں جمع ہوکرموٹی موٹی تحریروں میں بدل گئی تھیں۔
اس کی نفرت کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ کیوں جان دی تھی آپ کے والد نے؟ اس لیے کہ آپ کا باپ جیسا چچا ملیریا سے مرجائے؟ اس لیے کہ آپ کا بھائی نوکری نہ ملے تو ملک چھوڑجائے؟ اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو کراچی کے انجینئرنگ کالج میں اس لیے داخلہ نہیں ملے کہ اس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل اور پی آر سی ہے، چاہے نمبر کتنے بھی اچھے ہوں اورآپ کی بیٹی سندھ اور ڈاؤمیڈیکل کالج کے بجائے نواب شاہ میں پڑھے، کیوں کہ وہ سکھر یا لاڑکانہ کی نہیں ہے۔
وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اسی وقت انہیں احساس ہوا تھا کہ وقت کافی گزرگیا ہے۔ پلوں کے نیچے سے پانی اتنا گزرا ہے کہ نفرتوں کے سمندر بن گئے ہیں۔
انہوں نے احمد کو سمجھایا تھا ”مگر احمد، جو بھی ہے اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ہم نفرت کرنا شروع کردیں۔ پنجابیوں سے، سندھیوں سے، ہر ایک سے۔“
”پھر کس سے نفرت کریں؟“ احمد نے بڑے کٹے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ ”پی آئی اے میں پنجابی کام کرتے ہیں اورسندھ سیکریٹریٹ میں سندھی ہوتے ہیں۔ نفرت اس سے ہی کی جاتی ہے جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ پہلے سے اپنی برادری، اپنے گاؤں، اپنے گوٹھ سے لوگوں کوبلا کر رکھتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نفرت نہ کرو، یہ ساری باتیں کتابوں کی باتیں ہیں۔ اسکول میں پڑھانے کی باتیں ہیں، ان کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستان کتابوں میں ہوگا۔ علامہ اقبال اور قائداعظم کی قبروں میں ہوگا، یہاں پر کوئی پاکستان نہیں ہے، حقیقی زندگی میں پنجاب انٹرنیشنل ائرلائنز ہے، پنجاب آرمی ہے، پنجاب پولیس ہے اور جب تک اس طرح سے رہے گا، مہاجروں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔“ احمد کا چہرہ غصے سے سرخ اور غضب ناک ہو گیا تھا۔
”مگر احمد، اس نفرت سے نوکری تو نہیں ملے گی اور آخر کار نقصان کس کا ہوگا؟ ان کا ہی ہوگا جو تعلیم چھوڑدیں گے۔ تم کوسرکاری نوکری ہی کی کیوں تلاش ہے اوربھی تو نوکریاں ہیں، اوربھی تو لگ ہیں۔ اس شہرمیں رہنے والے عیسائی، پارسی، میمن یہ لوگ تو سرکاری نوکری کے پیچھے نہیں بھاگتے مگر رہ رہے ہیں نفرت کیے بغیر۔“
احمد بڑی نفرت سے مسکرایا، ”مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، آپ کی ٹیچری اور تعلیم نے آپ کو کیا دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر، دن رات کی محنت؟ میں نے بھی ٹیوشن پڑھا پڑھا کر اپنا خرچ پورا کیا ہے۔ میری پانچ بہنوں کی شادی کے لیے تھوڑی سی رقم بھی امی جان کے پاس نہیں ہے اور آپ اپنی شرافت اورمحنت کی راگنی الاپ رہے ہیں۔ شرافت کے اس ریکارڈ سے دنیا نہیں بدلتی ہے ابا جان۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے گی تو میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔
گھر کو تھوڑا بنالوں گا، بہنوں کی شادی کرادوں گا مگر روز بروز ایک گھن چکر کی چرخی میں گھومتا جا رہا ہوں۔ مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ نوکری ملتی ہے اورجو رشتہ آتا ہے اس کے ساتھ جہیز کی فرمائش اور چار سو پانچ سو آدمیوں کے کھانے کی بات ہوتی ہے۔ ایک ماسٹر کی بیٹی سے شادی کون کرتا ہے اورآپ مجھے نفرت نہ کرنے کی تلقین فرمارہے ہیں۔ ”
”احمد، جہیز کی فرمائش اورکھانے کا اصرار تو ہماری اپنی برادری والے کرتے ہیں۔ یہ سندھی اورپنجابیوں نے تو نہیں سکھایا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، علیحدہ بات ہے۔“
”نہیں کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے اور نہ کوئی علیحدہ بات ہے۔“ احمد نے بڑی جھنجھلاہٹ سے اپنی بات کہی تھی۔ ”ساری بات ایک ہے اس برادری اوران لوگوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اورپاکستان میں جو مسئلے ہیں اس کوسمجھتے ہیں۔ آپ کی مسلم لیگ اورآپ کی جماعت اسلامی کے لوگ اپنے بچوں کی شادیاں جس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے اورآپ نے دیکھا ہے۔ آپ اورآپ جیسے لوگ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، نہ سمجھیں گے نہ بدلیں گے۔ حالات بدل گئے ہیں۔ پاکستان اب نہیں رہا ہے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے اور اب سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، ہم لوگ کہیں بھی نہیں اور کوئی بھی ہمارا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو خوب بے وقوف بنایا گیا ہے۔ کبھی اسلام کے نام پر اور کبھی پاکستان کے نام پر۔ یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔“
وہ کیا کہتے، کیا جواب دیتے۔ کیا سمجھاتے، سوال سب تھے اور جواب صرف ایک۔ انہوں نے آگرہ میں ہی سیکھا تھا ایمانداری کا سبق، محنت اور ہر ایک سے محبت اور ہر کوئی ان سے محبت ہی کرتا تھا۔ مجھے بھی ان سے ایسی ہی محبت ہو گئی تھی جیسے کسی استاد سے کسی شاگرد کوہوتی ہے۔ میری پوری کلاس میرے سے پہلے کے طالب علم اورمیرے بعد کے طالب علم ان پر جان دیتے تھے۔ وہ ایسے استاد تھے مگر ان کا اپنا بیٹا احمد ان کی بات نہیں سمجھتا تھا۔
جب ہنگامے شروع ہوئے تھے تو محلے میں پنجابیوں کے گھر کوآگ لگوانے میں احمد سب سے آگے آگے تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ احمد ہی نے سب سے پہلے لوگوں کوجمع کر کے بھڑکایا تھا۔ گھروں میں آگ لگنے سے پہلے ہی پنجابی خاندان بھاگ کر گرین ٹاؤن چلے گئے تھے جو کہ پنجابیوں کی بستی تھی۔ جہاں سے اکے دکے رہنے والے مہاجر بھاگ کر شاہ فیصل کالونی میں آ گئے تھے۔
مگر اس دن کے بعد ماسٹر صاحب نے احمد کا داخلہ گھر میں بند کر دیا تھا۔ اس سے نہیں ملے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھا۔ اسے وہ اپنی ناکامی سمجھتے تھے۔ میں اکثر ان سے ملنے چلا جایا کرتا تھا۔ ان کے گھر کے اس چھوٹے سے کمرے میں ان کی چارپائی کے سامنے کی کرسی پر بیٹھ کر گھنٹوں ان کی بات سنا کرتا تھا مگر احمد والے واقعے کے بعد سے آہستہ آہستہ جیسے انہوں نے اپنی توانائی گنوادی تھی۔
احمد محلے میں ہی ایک اور گھر پر رہتا تھا۔ اس نے وڈیو کی دکان کھول لی تھی اوراس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کی غیرموجودگی میں جب وہ اسکول میں ہوتے تھے تو اپنی ماں اوربہنوں سے ملنے آتا تھا جس کی خبر ماسٹر صاحب کو نہیں ہوتی تھی۔ مگرآہستہ آہستہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ احمد کا گھر میں آنا جانا ہے۔ انہوں نے احمد کی ماں کو سمجھایا تھا تو انہیں یہی جواب ملا تھا کہ احمد نہیں آتا ہے۔ وہ اندر سے جیسے ٹوٹ سے گئے تھے۔
اس روز ماسٹر صاحب کے کمرے میں ان کی چارپائی کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ سخت بیمار تھے۔ ان کی دھنسی ہوئی آنکھیں، ان کے چہرے کا کرب، ان کی بے قراری کہہ رہی تھی کہ اب وہ نہیں بچیں گے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تھا۔ ان کی ذیابیطس، پھر دل کی پرانی بیماری اور دن رات کی ان تھک محنت اپنا پورا حساب مانگ رہی تھی۔ کچھ دواؤں کا انتظام میں چند ڈاکٹر دوستوں کی مدد سے کرتا رہا تھا اورکچھ وہ خود خریدتے رہے تھے۔ انہوں نے علاج معالجے کے لیے احمد کی طرف سے آنے والی رقم کی مدد لینے سے منع کر دیا تھا۔ آخر کی اس گھڑی میں انہوں نے اپنی بیوی شائستہ کوبلایا تھا۔ وہ پریشان صورت میرے سامنے بستر پربیٹھی دھیرے دھیرے رو رہی تھیں۔
ماسٹر صاحب نے شائستہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ ”شائستہ میرا وقت آ گیا ہے۔ اب میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ میں نے زندگی بھر سچ اورمحنت کی تبلیغ کی ہے، خدا اورمیرے بزرگوں کی روحیں گواہ ہیں اور تم گواہ ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد بھی احمد اس گھرمیں نہیں آئے گا۔ میری صورت نہیں دیکھے گا۔ میں نے اس کے لیے صرف دعا کی ہے اوراب بھی دعا کرتا ہوں یا رب اس کے دل سے نفرت نکال دے۔ نفرت نکال دے۔ نفرت نکال دے۔“
مجھے ایسا لگا کہ ان کی سانس پھول گئی ہے مگر وہ خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ میں نے سفید چادر سے ان کے جنازے کوڈھک دیا تھا اور روتی ہوئی ماسٹر صاحب کی بیوی کو چھوڑا، تجہیز و تکفین کے لیے مسجد جا کر خبر کی تھی پھر علاقہ کے پی سی او سے ماسٹر صاحب کے شاگردوں کو فون کرنے چلا گیا تھا۔
دو گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا ماسٹر صاحب کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا شامیانہ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف خواتین اور دوسری جانب مرد قرآن خوانی کر رہے تھے۔ اندر جیسے سکوت کا عالم تھا۔ کبھی کبھی ماسٹر صاحب کی چھوٹی بیٹی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ آنے والوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب میں احمد اپنے موبائل فون کے ساتھ بہت نمایاں تھا لوگوں سے ملنے میں۔ انہیں بٹھانے میں اور ان سے پرساد وصول کرنے میں۔
ماسٹر صاحب کی آخری خواہش شیشے کی طرح چکنا چور ہو کر بکھر گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تعصب اور سوگ کب تک ایک ہی شامیانے تلے رہیں گے۔
- گھمنڈی - 05/01/2024
- تم جیو ہزاروں سال - 25/12/2023
- ایک انگوٹھی - 21/12/2023

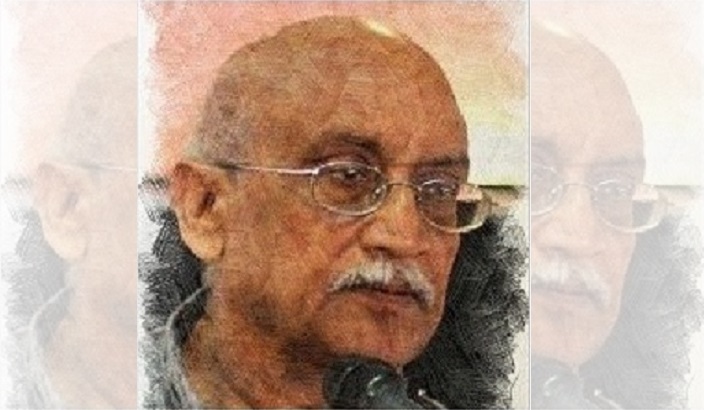

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).