شہر برباد کی دھول
بڑی سی واشنگٹن فلائر کی ٹیکسی کے لمبے چوڑے گورے چٹے ڈرائیور نے میرا سوٹ کیس اور بیگ اٹھا کر ڈگی میں ڈالا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ مجھے پیچھے بیٹھنے میں ہمیشہ کوفت ہوتی ہے۔ میں آگے کا دروازہ کھول کر آگے ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ بھی پچھلا دروازہ بند کر کے فوراً ہی اپنی سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔
”ہاؤ آر یو؟“ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
”الحمداللہ، فائن تھینکس گاڈ۔“ میں چونک گیا، کسی گورے کے منہ سے الحمداللہ؟
ڈیلس ائرپورٹ واشنگٹن پہنچ کر مجھے ٹیکسی پکڑنی تھی اور پراچہ کے آفس پہنچنا تھا۔ امریکا میں کلینک کو آفس کہتے ہیں۔ پراچہ ورجینیا میں آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، مجھے اس کے پاس ہی رہنا تھا اور واشنگٹن میں ہی ایک پانچ روزہ کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ یہ کانفرنس دنیا میں تہذیبوں کے عروج و زوال کے موضوع پر منعقد کی جا رہی تھی۔ کانفرنس میں نسل، ذات اور زبانوں کے نام پر قتل و غارت گری کے حوالے سے بھی بات ہونی تھی۔
یہ کانفرنس واشنگٹن میں کتابوں کے ایک ادارے اور واشنگٹن یونیورسٹی کے تعاون سے ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ تہذیبوں کے عروج و زوال پر ماتم کر کے کیا سیکھنا چاہ رہے تھے۔ ان کی تو تہذیب بھی محفوظ تھی اور انہوں نے تاریخ سے سیکھا بھی تھا جس کے مطابق وہ اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ہونی تو ہمارے ہاں چاہیے تھی جہاں تہذیبیں مٹ رہی ہیں، زبانیں موت کے گھاٹ اتاری جا رہی ہیں، نسلوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، ذاتیں، ذات کے نام پر ہی خاموشی سے مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
میں تاریخ پڑھاتا تھا اور تاریخ ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ پاکستان میں تاریخ پڑھانے والے پروفیسر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ واشنگٹن میں کسی کانفرنس میں جا سکے۔ صرف ہوائی جہاز کا کرایہ ہی میری چھ ماہ کی تنخواہ کے برابر تھا۔ پھر کانفرنس میں شمولیت کی فیس، واشنگٹن میں رہنے کا خرچہ اور اگر پاکستان سے باہر نکلنا ہو تو کچھ نہ کچھ خریداری بھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ ادھر یہ حال کہ یونیورسٹی کا پروفیسر دال روٹی کھا کر عزت سے گزارہ ہی کر لے تو کافی ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تاریخ کی کیا اہمیت ہے، اگر تاریخ کی اہمیت ہوتی تو ہمارا یہ حشر ہی کیوں ہوتا۔
تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا تھا ہم لوگوں نے، جب ہی تو ملک ٹوٹ گیا تھا، جب ہی تو شہر بظاہر بڑھ رہے ہیں مگر اندر سے ختم ہو رہے ہیں جیسے دیمک چاٹ جاتی ہے لکڑی کو ۔ اس خطۂ زمین کی تاریخ بھی عجیب تھی حکمرانوں کی تاریخ الگ تھی اور جنتا کی تاریخ الگ تھی۔ عوام موہنجوداڑو سے پہلے بھی غلام تھے اور موہنجوداڑو کے بعد بھی غلام ہیں اور حکمران طبقہ ہر دور میں حکمران ہی رہا تھا۔
پراچہ اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے۔ کراچی کی پی آئی بی کالونی میں پل کر بڑے ہوئے تھے، مجھے کیمسٹری اور بیالوجی سے الجھن ہوتی تھی اور اسے پورس کے ہاتھی اور اشوک کے چکر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا اور واشنگٹن میں آنکھوں کا ایک بڑا ڈاکٹر بن گیا تھا۔ میں نے تاریخ میں ایم اے کیا تھا، پھر صرف قسمت کا ہی چکر تھا کہ گوئٹے انسٹی ٹیوٹ سے مجھے جرمنی کا اسکالرشپ مل گیا اور میں نے یورپ کی تاریخ پر جرمنی میں پی ایچ ڈی کر ڈالی۔
وہ پانچ سال میری زندگی کے خوب صورت سال تھے۔ پورا یورپ، انگلینڈ، آئرلینڈ دیکھ لیا تھا۔ میں کمیونسٹ ممالک بھی جا کر دیکھ کر آیا تھا۔ پانچ سال تک پڑھا، ملک گھومے، بچت کچھ نہیں کر سکا، پاکستان واپس آیا تو ایک چھوٹا سا مکان جو والد صاحب سے ورثے میں ملا تھا میرا کل اثاثہ تھا اور وہ بھی ایسا تھا کہ اس میں کچھ مرمت، کچھ تبدیلیاں کر اکر رہ سکوں۔ پراچہ نے ہی مجھے اس میٹنگ کے لیے بلا لیا تھا۔ میرا ٹکٹ بھی خریدا، کانفرنس کی فیس بھی دی اور کانفرنس کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی کر کے امریکا گھمانے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ ہماری بچپن کی دوستی میں اس کی مصروفیت کوئی خاص برا اثر نہیں ڈال سکی تھی۔
پروگرام یہی تھا کہ میں ڈیلس ائرپورٹ سے پراچہ کے آفس پہنچ جاؤں گا پھر وہاں سے کچھ دیر کے بعد پراچہ کے گھر چلیں گے پھر باتیں ہوں گی اور مزید پروگرام بنے گا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ ائرپورٹ پر واشنگٹن فلائر کی ٹیکسی مل جائے گی۔ وہ خود نہیں آ سکتا تھا کیوں کہ اسے ایک آپریشن کرنا تھا۔
ڈرائیور کے الحمدللہ سے میں یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی امریکن مسلمان ہے۔ آج کل امریکا میں ہر سال ہزاروں لوگ مسلمان، بدھسٹ، ہری راما ہری کرشنا اور چین کے مختلف مذہب اپنا رہے تھے۔ جن سماجوں میں دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور سننے کی برداشت ہوتی ہے، وہاں کے لوگ اپنے مذہب، اپنے اعتماد، اپنے یقین سے اکتا جاتے ہیں اور ایک اقلیت مذہب تک بدل دیتی ہے یا لامذہب ہوجاتی ہے۔ امریکا، یورپ، جاپان میں یہی ہو رہا تھا۔ سائنسی ترقی اور مادی آسائشوں نے روحانی خلا پیدا کر دیا تھا جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا تھا کہ کیا وہ امریکن ہے؟
اس نے جواب دیا تھا نہیں امریکن نہیں افغانی ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ واشنگٹن میں افغانی ڈرائیور سے ملاقات ہو جائے گی۔ افغانستان تو ہمارا پڑوسی ملک تھا اور میں ایک دفعہ شاہ ظاہر شاہ کے زمانے میں افغانستان جا بھی چکا تھا اور اب جو کچھ وہاں ہو چکا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تباہی کے وہ بادل پاکستان بھی آئیں گے۔ ابھی بادلوں کی کمی ہے۔ وہ جمع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ گھنگھور گھٹا بن کر چھا جائیں گے اور جب چھٹیں گے تو بہت کچھ لٹ چکا ہو گا۔
میں نے پوچھا، ”کب آئے آپ افغانستان سے؟“ میں پاکستان سے آیا ہوں اور کابل، قندھار خوب گھوم چکا ہوں، جب اچھے حالات تھے وہاں کے۔ ”میں نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے بات بڑھائی تھی۔
”میں قندھار کا رہنے والا ہوں۔ آپ پاکستان میں کہاں سے آئے ہیں؟ میں کراچی کے منو ہوٹل میں رہ چکا ہوں۔ آپ جانتے ہو منو ہوٹل۔“ اس نے سوال کیا تھا، ”مکی مسجد کے پاس ہے۔“ اس نے خود ہی جواب بھی دے دیا تھا۔
”میں کراچی کا ہی ہوں مگر اب منو ہوٹل ہسپتال بن گیا ہے۔ کراچی میں ہوٹل، سینما، پارک، سب ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اب صرف پاگل خانے، ہسپتال اور گندی گندی عمارتیں بن رہی ہیں۔“ میں نے ہنس کر جواب دیا۔ ساتھ ہی پوچھ لیا کہ آپ منو ہوٹل میں کیا کر رہے تھے؟
”امریکا آنے سے پہلے بہت جگہ جانا پڑ گیا، کراچی بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے۔ ہم افغانیوں کی ایسی ہی کہانی ہے۔ اب کوئی وطن نہیں ہے ہمارا، نہ کوئی زمین ہے۔ ساری دنیا میں جس طرح سے ہم لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں ہوا ہو گا۔ ہماری خواتین ہوٹلوں میں کام کر رہی ہیں، ہماری قوم بین الاقوامی سطح پر مفلوک الحال ہو کر رہ گئی ہے۔ اچھوت جنہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں جو خود اپنا وقار اپنی نظروں میں کھو چکے ہیں۔ لمبی کہانی ہے چھوڑیں اس نے جواب دیا تھا۔
”کہانیوں سے تو مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ نہیں مجھے بتائیں کیا ہوا تھا۔“ میں نے بڑی دلچسپی سے کہا۔ ”مجھے ابھی تک قندھار یاد ہے۔ میں وہاں رمضان کے زمانے میں گیا تھا اور توپ خانہ بازار کے پاس ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور مجھے یاد ہے رمضان کا زمانہ تھا، سارا شہر رات بھر جاگتا تھا۔ تراویح کے بعد ہوٹلوں میں موسیقی چلتی رہتی تھی اور فنجانوں میں لوگ چائے پیتے رہتے تھے۔ اب تو مجھے یاد نہیں ہے گانے والوں کا نام مگر کچھ نام ابھی تک یاد ہیں۔ احمد ظاہر، احمد ولی، رحیم بخش اور استاد قاسم۔ ارے ہاں میں نے وہاں کے منزل باغ سینما میں دلیپ کمار کی فلم“ داستان ”بھی دیکھی تھی۔ وہی میری زندگی کی پہلی ہندوستانی فلم تھی۔“
وہ لمبی سیاہ شاہراہ پر دور نظر جمائے ٹیکسی چلارہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے ہیں اور آنسوؤں کے دو قطرے ٹپک کر گالوں پر پھیل رہے ہیں۔ میں نے شاید اس کو دکھی کر دیا تھا۔ اس نے ٹشو پیپر نکال کر آنسو پونچھے تھے اور بڑی گلوگیر آواز میں بولا تھا: ”سب ختم ہو گیا۔ اب توپ خانہ بازار اور باغ پل پر زندگی مر چکی ہے۔ منڈی بازار میں سناٹا ہے اور منزل باغ کا سینما ختم کر کے وہاں مسجد بنا دی گئی ہے۔
سب ختم ہو گیا افغانستان میں۔ میں تو ہوں ہی قندھار شہر کا اور آپ نے جو یہ سارے نام لیے تو جیسے میرے سینے پر گولی ماری ہے۔ وہ ساری چیزیں میرے سامنے آ گئی ہیں اور دل رونے لگا ہے۔“ اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ بڑی عجیب کہانی ہے میری۔ میں کابل یونیورسٹی میں فزکس پڑھاتا تھا۔ اور اب واشنگٹن کی سڑکوں پر ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کابل یونیورسٹی کے پروفیسر کپڑوں اور قالینوں کا بازار لگاتے ہیں، اسکول استاد برگر بیچتے ہیں اور ہوٹلوں میں ویٹر بن گئے ہیں۔ فوج کے کرنل اور جنرل اور ایئر کموڈور دنیا کے شہروں شہروں میں مسافر بن کر وظیفوں پر زندہ ہیں۔ ”
ہماری بچیاں جو وہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں یہاں بڑے بڑے اسٹوروں میں سیلز گرل بن گئی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ۔ دنیا کے ہر ملک میں افغانی موجود ہیں۔ وہ ہر کام کرتے ہیں، جھاڑو لگانے سے لے کر عزت بیچنے تک۔ پیٹ سب کچھ کراتا ہے۔ میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ کہاں کہاں پر کس کس طرح کیا کیا کر رہے ہیں نہ آپ کو اندازہ ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کو اندازہ ہے جو ان سب چیزوں کے ذمے دار ہیں اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کی تو مثال ہی شاید کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ”
”آپ کیسے نکلے تھے؟“ میں نے انہیں بیچ میں روک کر پوچھا تھا۔
”یہ سب کچھ یکایک ہی ہو گیا تھا۔ روسیوں کے جانے کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ اب کچھ امن و امان ہو جائے گا۔ اب دوبارہ زندگی سانس لے گی، اب دوبارہ سڑکوں پر رونقیں بحال ہوں گی، دوبارہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم کا دور دورہ ہو گا، دوبارہ لوگ غریب ہوں گے مگر ذہن و دل کے امیر ہوں گے مگر یہ کچھ نہیں ہوا۔ ایک تیسری جنگ، ایک اور بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی اور ایسی صورت حال ہو گئی کہ ہر پڑھے لکھے ہنر مند قابل آدمی کو افغانستان چھوڑنا پر گیا تھا۔
میں بھی کسی نہ کسی طرح سے بھاگ کر کابل سے نکلا تھا۔ کسانوں کی طرح کے کپڑے پہن کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ رات کے اندھیرے میں کھیتوں، وادیوں کو پھلانگتے ہوئے ء، ندی نالوں کو پھلانگتے ہوئے کھاڑیوں سے اور مجاہدین سے بچتے ہوئے قندھار سے ہو کر چمن اور پھر کوئٹہ پہنچ گیا تھا۔ کس کس طرح سے میں نے اپنی بیوی کی حفاظت کی ہے اس کا سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ میرے کتنے ہی ساتھی کابل یونیورسٹی کے گولیوں کا نشانہ بن گئے، ان کی بیویاں طوائف ہو گئیں، ان کے بچے بھکاری بن کر رہ گئے ہیں۔ قندھار جانا ضروری تھا، کچھ سونا تھا، ماں باپ کے زیورات تھے جن کا لے جانا ضروری تھا کیوں کہ بغیر پیسے کے ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے۔“
وہ ذرا دیر کے لیے رکا، ”ساری باتیں تو بتانا مشکل ہے، مہینے گزر جائیں گے کہانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ صرف واشنگٹن میں ہی تیس ہزار افغانی ہیں اور تیس ہزار کہانیاں ہیں۔ پھر آپ کی بتائی ہوئی جگہ بھی آ جائے گی۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج بہت دنوں کے بعد آپ نے مجھے رلا دیا ہے۔ میں پٹھان آدمی ہوں اور پٹھان مرد روتے نہیں ہیں۔ مگر آج ہم افغانیوں کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔“ اس نے رک رک کر کہا۔
”کوئٹہ میں ہی ایک ایجنٹ عبدالولی سے ملاقات ہوئی اور اس نے کراچی میں ایک ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرایا تھا۔ اور ہم لوگ ٹرین سے کراچی آئے اور منو ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ سونے کے زیورات بیچ کر جو بھی ہمارے پاس تھا اور دوسرے رشتے داروں سے ادھار لے کر دو دو لاکھ میں طے ہوا اور ہم لوگوں کو سوئیڈش پاسپورٹ مل گیا تھا اور ساتھ میں ٹکٹ بھی۔ وہ پاسپورٹ جعلی تھے، ان پر ویزا بھی جعلی تھا۔ ہم لوگ کراچی سے نکلے، ترکی پہنچے، ترکی سے اٹلی اور اٹلی سے سیدھا نیویارک۔
نیویارک ائرپورٹ پر ہی ہم نے امریکن پولیس کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ سویڈن کے نہیں ہیں بلکہ جعلی ویزے پر سوئیڈش بن کر آئے ہیں۔ ہم لگ افغانی ہیں اور سیاسی پناہ چاہتے ہیں۔ چھ گھنٹے کے انٹرویو کے بعد ہمیں رہنے کی اجازت ملی تھی۔ ایجنٹ نے ہی نیویارک کے ایک یہودی وکیل کا پتا بتایا تھا جس کو ہم نے ائرپورٹ سے ہی فون کر دیا تھا۔ اس کے لوگ پہنچ گئے تھے۔ وکیل کو دینے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس مگر نیویارک کا نظام بہت اچھا ہے اور یہودی وکیل اپنے کام میں پکے ہیں۔ انہوں نے ہم سے صرف یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو بعد میں قسطوں میں پانچ ہزار ڈالر دینے ہوں گے جب نوکری کی اجازت ملے گی اور ایک معاہدہ بھی دستخط کرایا تھا اس نے۔
چھ گھنٹے کے بعد امریکن حکومت کے خرچے پر ہی ایک سیاہ پناہ گزینوں کی پناہ گاہ میں ہم لوگوں کو رکھ لیا گیا تھا اور اس یہودی وکیل نے تین ہفتے میں ہی ورک پرمٹ کا انتظام کرا دیا تھا۔ اب ہم لوگ امریکی حکومت کے مہمان تھے، کام کر سکتے تھے، بینک سے ادھار لے سکتے تھے، ہم سب کو سوشل سیکیورٹی کا نمبر مل گیا تھا۔ اب تو سات سال ہو گئے ہیں اور گرین کارڈ بھی بن گیا ہے اور تھوڑے دنوں میں امریکن پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔
ووٹ بھی دے سکیں گے ہم لوگ۔ ہزاروں سال میں جو حق افغانستان میں نہیں ملا تھا وہ یہاں چند سالوں میں مل گیا ہے۔ ”یہ کہہ کر انہوں نے لمبی سانس لی اور گاڑی میں لگے ہوئے فون پر کسی کو فون کر کے پراچہ کے آفس جانے کا راستہ سمجھا تھا پھر فون رکھ کر کہا،“ اب ہم لوگ سب امریکن ہیں، بچے امریکن اسکولوں میں جاتے ہیں، میری بیوی نے ایم اے کیا تھا اور کابل کے دفتر خارجہ میں کام کرتی تھی، اب وہ کے مارٹ میں کام کرتی ہے اور میں فزکس پڑھاتا تھا، واشنگٹن کی سڑکوں پر ٹیکسی چلاتا ہوں۔
اگر آپ کو فرصت ہو اور آپ کو افغانوں کو دیکھنا ہو تو اتوار کو مجھے ملیں میں آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر دکھاؤں گا جو پارکنگ لاٹ میں گاڑیوں کو پارک کراتے ہیں، وہ جج دکھاؤں گا جو ہوٹلوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں، وہ افغانی عورتیں دکھاؤں گا جو ریسٹورنٹ میں ٹیبل صاف کرتی ہیں۔ اس ملک میں ڈالر کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ڈالر چاہیے اور ڈالر درختوں پر نہیں اگتے ہیں۔ اب زیادہ دور نہیں ہیں ہم لوگ۔ ”اس نے گاڑی ہائی وے سے چھوٹی سڑک پر گھماتے ہوئے کہا۔
میں بھی باتوں باتوں میں تقریباً کھو گیا تھا ایک طرف سنتا جا رہا تھا دوسری جانب ذہن نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں سوچ رہا تھا، طرح طرح کے خیالات ذہن کو جھٹکے دے رہے تھے۔ میں جو تاریخ کا پروفیسر تھا، تہذیبوں کے زوال و عروج پر کانفرنس میں شمولیت کے لیے واشنگٹن آیا تھا، میرے ملک کے برابر میں ایک اپنی تہذیب مٹی میں مل رہی تھی جس کے سپوتوں نے ہندوستان سے ترکی تک ہماروں سال حکومت کی تھی، جن کی زبان میں چاشنی تھی، جن کے گیتوں میں بلا کا درد تھا، جن کے شاہوں کے دربار میں علم و فضل کی رسائی تھی، جن لوگوں پر دنیا کی کوئی اور قوم حاکم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے ہیں۔ زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرح جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی جو لوگوں کی ٹھوکروں کی مرضی سے اپنے راستے کا تعین کرتا ہے۔ مجھے ایک شدید دھچکا سا لگا۔ میرے ذہن میں سوال آیا تھا اور میں پوچھ بیٹھا تھا کہ اگر افغانستان کے حالات صحیح ہوجائیں تو تم واپس جاؤ گے؟
اس نے کہا، ”ضرور جاؤں گا، فوراً جاؤں گا۔ یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرا کلچر نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، یہاں میری ماں کی قبر نہیں ہے، میرے دادا کا مکان یہاں نہیں ہے، میں کیا، میرے خیال میں ساٹھ ستر فیصد سے زیادہ افغانی فوراً واپس چلے جائیں گے۔ اگر ہمارا پرانا کابل ہمیں مل جائے۔“ اس کی آواز پھر بھرا گئی۔ ”مگر حالات اب کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ افغانستان کی موت ہو گئی ہے وہاں سولہ سترہ سال کے بچے قاضی بن گئے ہیں، وہاں ایک شہادت پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے وہاں سرعام لوگوں کو درختوں سے لٹکا کر پھانسی دی جاتی ہے، وہاں عورتوں کو گھر میں غلام بنا دیا جاتا ہے۔
وہاں اب ایک ایسی حکومت ہے جو مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بتوں سے خوف زدہ ہے جو پہاڑوں میں کاٹے گئے ہزاروں سالوں سے ایستادہ گوتم بدھا کے غیر مسلح مجسمے سے جنگ کر رہی ہے جو بھوک کے عفریت سے خوف زدہ ہے، جو غربت کے عذاب سے جنگ نہیں کرتی، جو نا انصافی کے چنگل سے نہیں نکلنا چاہتی، جو صدیوں کی جہالت کو مستقل کرنا چاہتی ہے، جو دنیا بھر کے خلاف ہے مگر دنیا بھر سے بھیک لینے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں رکھتی ہے۔
وہاں اب ایسی حکومت ہے جو افغانستان کو اس قبائلی دور میں واپس لے گئی ہے جہاں پیغمبروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب پیغمبر نہیں آئیں گے اور افغانستان تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اخبار تو پڑھتے ہوں گے، کبھی بی بی سی بھی سنتے ہوں گے۔ ریڈیو ایران کی آواز بھی آتی ہوگی، وائس آف امریکا کی آواز بھی آتی ہوگی، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو پاکستانی ہیں ناں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی فوج نے آپ کے ملک کے ان حکمرانوں نے جو جنگ روسیوں سے شروع کی تھی، وہاں ختم ہوئی ہے؟ اب وہاں پاکستان کے تربیت یافتہ ان طالبان کی حکومت ہے جن کا ذہن لوگوں کے ہاتھ کاٹ سکتا ہے، درختوں پر پھانسی لگا سکتا ہے۔ اسکولوں، یونیورسٹیوں کو بند کر سکتا ہے۔ عجائب خانوں کو مسمار کر سکتا ہے۔ وہ ہم افغانیوں کو مستقبل نہیں دے سکتا ہے، ایک ایسا مستقبل جس پر ہم فخر سے اپنے سربلند کرسکیں۔“
تھوڑی دیر وہ بھی خاموش رہا تھا اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا، مگر پھر پوچھا کہ آخر کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ اس کے جواب نے مجھے دوبارہ چونکا دیا تھا۔ ”یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ میں نے ساری زندگی فزکس پڑھائی ہے۔ توانائی کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کائنات کی ابتدا اور کائنات کی انتہا کے معموں پر غور کرتا رہا ہوں۔ اب بھی جب ان سڑکوں پر ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہوں تو کابل کی کوئی صبح، کوئی شام، کوئی تھکی ہوئی دوپہر یاد آجاتی ہے جب کابل یونیورسٹی میں کوئی لڑکا یا لڑکی مجھ سے پوچھتے تھے کہ آئن اسٹائن کے انرجی کے قوانین کے مطابق کیا انرجی کے لیے سورس کا ہونا ضروری ہے؟
کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کیا زمینی کشش کی طرح دوسرے سیارے کشش رکھتے ہیں؟ کیا انسان کبھی چاند سے بھی اوپر جا کر دوسری دنیاؤں میں پہنچ سکے گا؟ کیا کبھی بلیک ہول کی اصلیت کا پتا چل سکے گا؟ کابل کی وہ یونیورسٹی ویانا کی یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی یا ہارورڈ کی طرح سے مالامال یونیورسٹی نہیں تھی۔ مگر احساس امن تھا وہاں پر تعلیم کی کشش تھی، وہاں زندہ رہنے اور زندہ رہنے دینے کی روایات تھی۔ وہاں پر اب جہالت کا ایک بہت بڑا بلیک ہول بن کر رہ گیا ہے۔
جہل کی ہر چیز کھنچ کھنچ کر چل رہی ہے اور کوئی نہیں ہے ذمہ دار اس کا ۔ ہم افغانی، صرف افغانی ہی ذمہ دار ہیں اس کے۔“ لمبی سیاہ سڑک لگتا تھا کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی نظریں روڈ پر جمی ہوئی تھیں اور لگتا تھا کہ ذہن کہیں دور بہت دور گھوم رہا تھا میں نے کن انکھیوں سے دیکھا، اس کے آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ بے وطن بے زمین آدمی کے آنسو ایسے ہی ہوتے ہوں گے، ایسا ہی کرب ہوتا ہو گا دلوں میں جس کو اگر چھیڑ دیا جائے تو چھلک جاتا ہے اس طرح سے۔ مجھے دل ہی دل میں افسوس سا ہونے لگا تھا۔
یہ روسیوں کا کام ہے اور نہ امریکیوں کا ، یہ توہ مارا ہی کیا دھرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بولا۔ ”اس کا ذمہ دار نہ پاکستان ہے اور نہ ہی ایران، یہ افغان قوم ہی ذمے دار ہے اس کی۔ دنیا میں ایسی بہت کم قومیں ہوں گی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خون بہایا ہو گا، پانی کی طرح۔ امیروں نے بھی، غریبوں نے بھی، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی، جاہلوں نے بھی، کمیونسٹ اور دھریوں نے بھی، مذہبی ملاؤں اور طالبان نے بھی۔
داؤد کوئی بڑا انقلابی نہیں تھا۔ ظاہر شاہ کا رشتے دار تھا۔ ناظم حکمت سے لے کر ببرک کا رمل تک اور حفیظ امین سے لے کر ترہ کئی تک اور اب طالبان سے لے کر شاہ مسعود تک یہ سارے کے سارے افغانی ہیں مگر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ کوئی امریکا کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی ایران کے لیے لگا ہوا ہے اور کوئی پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ افغانیوں کی جنگ، میری جنگ، میری بیوی کی جنگ، میرے بچوں کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جس قوم کے لوگ اپنی ہی قوم کے خلاف غیروں کی جنگ لڑتے ہیں انہیں تباہی اور بربادی کے سوا کیا مل سکتا ہے؟“ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، خون کا سمندر اس کے چہرے پر موجیں مار رہا تھا۔
”ہم سب بے غیرت ہیں۔“ اس نے بڑے غصے سے کہا۔ پھر میری منزل آ گئی۔ پراچہ کے کلینک کے سامنے گاڑی رک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک سرخی نمایاں تھی اس کے اندر کا درد ابھی تک اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ ٹیکسی دیکھ کر اندر سے پراچہ کی سیکریٹری باہر آ گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے ٹیکسی کا کرایہ دے دیا۔
پانچ دن کی کانفرنس بہت اچھی تھی، ساری دنیا سے تاریخ داں آئے ہوئے تھے۔ لاطینی امریکا کے، مایا تہذیب سے لے کر اہرام مصر کی کہانی دہرائی گئی تھی، اجنتا کے غاروں سے آسٹریلیا کے ابروجنیز کا ذکر کیا گیا تھا۔ یمن کی عمارتوں سے لے کر موہنجوداڑو کی تعمیرات کے معجزوں پر غور کیا گیا تھا۔ ہلاکو خان سے سکندر اعظم تک کیا ہوا تھا، ہٹلر سے ویت نام تک ایک ہی کہانی تھی، قومیں، نسلیں، ذاتیں، ثقافتیں، تمدن، زبان، تہذیب، مذہب، اعتقاد، ایمان، یقین سب اسی وقت تباہ ہوئے جب انسانوں نے آپس میں جھگڑا شروع کیا، اپنے اندر سے فساد کا آغاز کیا۔
ہر آغاز کا نام نیا، پر انجام مختلف نہیں تھا۔ قتل و غارت گری، عورتوں کی پامالی، بچوں کی رسوائی، بوڑھوں کی کسمپرسی اور جوانوں کے خون کا نذرانہ۔ تاریخ تو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر نہ جانے کیوں انسان سمجھتا نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس سے وائٹ ہال تک، کریملن سے تن من اسکوائر تک، اسلام آباد سے دلی تک، تل ابیب سے بیروت تک اور نکاراگوا سے پیرس تک۔ ساری کانفرنس کے دوران میں سنتا رہا، سمجھتا رہا اور سوچتا رہا تھا۔
کانفرنس کے اختتام پر مجھے کابل یونیورسٹی کا وہ پروفیسر بہت یاد آیا جو واشنگٹن میں ٹیکسی چلاتا ہے۔ اس کا تو نام بھی نہیں پوچھا تھا میں نے۔ مگر نام میں کیا رکھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں افغان مہاجروں کے کوئی نام تھوڑی ہیں، سب مہاجر ہیں اور سب اس ٹیکسی ڈرائیور کی طرح بے سکون، بے اطمینان، بے منزل، بے مکان۔
میں نے پراچہ سے پوچھا تھا کہ واشنگٹن کی سڑکوں، محلوں، بازاروں اور مضافاتی علاقوں کا نقشہ سمجھنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کیا وہ مجھے ادھار پر ہی صحیح ایک ٹیکسی دلا دے گا؟ جب پڑوس کا طوفان ہمارے پاس بھی پہنچے گا، سرحد کے اس طرف پشاور سے کراچی تک، جب کراچی یونیورسٹی میں بھی مٹی اڑے گی، جب کراچی بھی کابل کی طرح، جب لاہور ہرات کی طرح، جب کوئٹہ قندھار کی طرح دھول دھول ہو کر بکھرنا شروع ہو گا، جب نیویارک کا وہ یہودی وکیل مجھے بھی سیاسی پناہ دلا کر امریکا میں کام کرنے کا ورک پرمٹ دلا دے گا تو میں اس فزکس کے پروفیسر کی طرح واشنگٹن کی سڑکوں پر اپنی قوم کی بے غیرتی کی کہانی سناؤں گا کیوں کہ تاریخ پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہو گا۔
پراچہ ہنس پڑا۔ بڑے زور سے، بڑی بے یقینی کے ساتھ۔ وہ ڈاکٹر تھا آنکھوں کی بیماریوں کا ماہر، آنکھوں کے اندر ایک عدسہ ہوتا ہے اس کے آپریشن میں یکتا۔ اسے میری طرح سے کیمسٹری بیالوجی سے نفرت نہیں رہی تھی، اسے سکندر اعظم اور راجا پورس کی جنگ سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تاریخ نہیں پڑھی تھی۔
اس لیے وہ ہنس رہا تھا اور میری آنکھوں میں دھول اڑ رہی تھی، لٹے ہوئے قریوں کی دھول۔
- گھمنڈی - 05/01/2024
- تم جیو ہزاروں سال - 25/12/2023
- ایک انگوٹھی - 21/12/2023

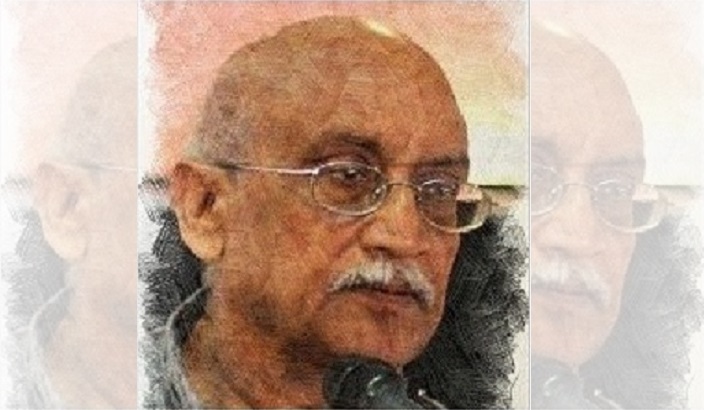

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).