زخمی عورت کا پیشاب
وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ دانت ٹوٹے ہوئے، ہونٹ پھٹے ہوئے، دونوں آنکھوں کے گرد خون جمع ہوا۔ ایک طرف کا کان نیچے سے کٹا ہوا، ناک سے خون بہہ کر ہونٹوں پر جم کر پپڑی سا بن گیا تھا، گردن پر زخموں کے نشان، چھاتیوں کو بڑی بے دردی سے شاید گھونسے مارے گئے تھے، پیٹ، کمر، رانوں اور کولہوں کو شاید جوتے والی لاتوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھرے ہوگئے، میں بھی پٹتی رہی تھی لیکن اس طرح سے مجھے نہیں مارا تھا میرے شوہر نے۔ مجھے اس کی تکلیف دیکھ کر رونا آ گیا۔ بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں اپنے آنسوؤں کو روک کر رکھا تھا میں۔
جلد ی جلدی نرسوں کی مدد سے میں نے اس کے زخم صاف کیے، کٹے ہوئے کان پر پانچ ٹانکے لگائے، سر کے زخم کی مرہم پٹی کی، پیٹ اور کولہوں کے زخموں کو صاف کیا، جہاں بینڈیج کی ضرورت تھی وہاں بینڈیج لگائی، جہاں صرف صفائی کرنا تھی صفائی کی۔ وہ بول نہیں پارہی تھی کیوں کہ اس کی زبان کئی جگہوں سے کٹی ہوئی تھی، میں نے اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگائی اور درد دور کرنے کے لیے انجکشن لگائے۔ اس کی غنودگی نیند میں بدل گئی۔
اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ شہر کے اچھے رہائشی علاقے سے لائی گئی تھی، ایمبولینس کے کارکنان نے بتایا کہ اس کا تعلق انڈونیشیا سے تھا اور کسی امیر عربی شیخ کے گھر کی ملازمہ تھی۔ گھر میں ہی کسی وجہ سے اسے مارا پیٹا گیا تھا۔ اور جب وہ تقریباً بے ہوش ہوگئی تو ایمبولینس بلا کر اسے ہسپتال بھجوادیا گیا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، شاید تیس سال ہوگی، ناک نقشے سے وہ جاذب نظر تھی، مار لگنے سے پہلے اسے ضرور خوبصورت لڑکیوں میں شمار کیا جاتا ہوگا، میرے دل میں جیسے ایک مامتا سی ابل پڑی۔ نہ جانے اسے کیوں مارا گیا، کس نے مارا اور اس طرح سے مارا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر بار بار روہانسی سی ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی میں نے اس کے ایکس رے اور اسکین کے کارڈ بنائے، وہ زخمی ضرور تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ اسے ریڈیولوجی کے شعبے میں بھیج کر میں اپنے کمرے میں آکر آرام کرسی پر ڈھیر ہوگئی۔
میری شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ میں ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی، خوبصورت، امیر تو نہیں لیکن شریف گھرانے سے تعلق تھا۔ چار بہنوں کی سب سے بڑی بہن۔ ماں باپ نے بڑے چاؤ اورمحبت کے ساتھ مجھے گھر سے رخصت کیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سسرال جو بظاہر انہیں نظر آیا تھا وہ سسرال ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ ڈاکٹر بہو تو لے کر آئے مگر ساتھ ہی انہیں ایک اچھے جہیز کی بھی امید تھی جو میرے ماں باپ کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک پڑھے لکھے گھرانے کے ایک پڑھے لکھے کمپیوٹر انجینئر سے شادی کی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پڑھی لکھی بہو کو خوش آمدید کریں گے۔
مگر ایسا نہیں ہوا، پہلے ہی دن سے مجھے مناسب جہیز نہ لانے کے طعنے ملے، پھر شوہر نے بھی کہہ دیا کہ اگر فلیٹ، فرنیچر اورکار نہیں دیا تو کم از کم کچھ کیش رقم ہی دیا ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کی زندگی بن جاتی ہے، میری شادی ہوئی ہے تومجھے کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ شادی کا فائدہ کیا ہوا اس سے تو اچھا تھا کہ میں کنوارا ہی رہتا، کیسی قسمت ہے میری، اس نے شکوہ کیا تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ مجھے پتا تھا کہ شادی سے پہلے میرے امی ابو نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ سب کچھ ظاہر کر دیا تھا۔ سب کچھ بتادیا تھا، ایک اسکول کے استاد کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، چھ بچے، غریب بیوہ پھوپھی اوران کے بچوں کا بوجھ، گھرکا خرچہ، ہم چھ بھائی بہنوں کی پڑھائی کا خرچہ اورپھوپھی کے چار بچوں کی زندگی کا چرخا۔ سب کچھ تو بتادیا گیا تھا۔ مگر میرے سسرال والوں کا خیال تھا کہ ہم لوگ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہوں گے کہ ایم بی بی ایس کی ڈگری کو جہیز کے برابر سمجھیں گے۔
میں شروع سے ہی بڑی حساس تھی، بڑی ہونے کے ناتے مجھے اسکول کے زمانے سے ہی اندازہ ہوگیا تھا کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے امی ابو کو ایک دم سے بوڑھا ہوتا ہوا دیکھا۔ ان کی ہنسی، شوخی، امنگ، جوانی سب کچھ ان ٹیوشنوں کی نظر ہوگئی۔ جس کے لیے نہ جانے وہ کہاں کہاں مارے مارے پھرا کرتے تھے۔ پھوپھو کے بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے ان کی ذمہ داری بھی لے لی تھی۔ امی کی طرح پھوپھو بھی خانہ داری کرنے والی گھریلو خاتون تھیں۔ بڑے صبراور محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا، اپنے بھائی اور میرے والد کی زندگی بھر قدر کی، زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل نکلی، اس امید کے ساتھ کہ مستقبل ضروراچھا ہوگا۔ سب بچے پڑھ لیں گے، پھر کچھ سکون کے دن آ جائیں گے ہماری زندگیوں میں۔
میں دونوں گھروں کی بڑی لڑکی تھی، سارے چھوٹے بھائی بہنوں کی رول ماڈل۔ ہمیشہ اچھے نمبر لے کر امتحانوں میں پاس ہوئی، میڈیکل کالج میں بڑی محنت سے پڑھائی کے ساتھ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا پڑھا کر ابو کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی رہی، بڑی امیدیں تھیں سب کو میری شادی سے، سب کا خیال تھا کہ بڑا داماد گھر کا بڑا بن جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سسرال میں شروع دن سے ہونے والی زیادتی کو میں چھپاگئی۔ کسی سے کچھ نہیں کہا اور دوسری نہ جانے کتنی بیوقوف لڑکیوں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔
کچھ بھی صحیح نہیں ہوا۔ امی ابو پھوپھو یہ سمجھتے رہے کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں اورمیں یہ کوشش کرتی رہی کہ اپنے شوہر کو سمجھالوں اسے اپنالوں، اسے یہ باورکرادوں کہ میں ڈاکٹر ہوں کام والی ہوں مل جل کر ہم دونوں کمائیں گے سب کچھ کر لیں گے زندگی میں، مری مرائی لیڈی ڈاکٹر بھی اچھے پیسے کمالیتی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوسکا تھا۔ نہ جانے ہمارے سماج میں لڑکوں کو ایسا کیوں بنایا جاتا ہے، مائیں یہ سوچتی کیوں نہیں ہیں کہ یہ ان کا بگڑا ہوا بیٹا ان کی کسی بہن کا داماد بنے گا، کسی کی بیٹی کا شوہر ہوگا، کچھ اس بیٹی کے بھی تو حقوق ہوں گے؟ اسے بھی تو انسان ہی سمجھنا چاہیے، کیا صرف مرد انسان ہوتے ہیں؟
ایک دن میں نے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جس گھر کو میں اپنا سمجھتی ہوں ا س گھر میں مجھے اگر طعن تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا تو کیسے کام چلے گا۔ ٹھیک ہے میں جہیز نہیں لائی ہوں، مگر میں ڈاکٹر ہوں بہت کچھ کرلوں گی، بس تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، تھوڑا انتظار کرلو میری تعلیم مجھے سب کچھ خرید کر دے گی، ہم دونوں مل کر وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔
اس دن مجھے پہلی بار مارا تھا میرے شوہر نے، ”میں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا۔“ حالانکہ میں نے ان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، صرف یہ خواہش کی تھی کہ طعن و طنز نہ ہوں۔ مجھ پر لفظوں کے تیر نہ چلائے جائیں۔ تھوڑی سی عزت دینے میں کیا بگڑجائے گا؟
اس کے بعد اس کا ہاتھ کھل گیا تھا۔ لیکن جس طرح سے یہ لڑکی زخمی آئی تھی اتنے زخم مجھے کبھی بھی نہیں ملے تھے۔ نہ جانے کون تھی بے چاری اور کیوں مارا تھا اس کے مالکوں نے اسے۔ میں سوچتی رہی تھی۔ میرے سلسلے میں تو ایک وجہ تھی میرا شوہر اور اس کا خاندان سمجھ رہا تھا کہ میں جہیز لے کر آؤں گی مگر ایسا نہیں ہوسکا تھا۔ شکوے شکایات طنز اور طعنوں سے بات مارپیٹ تک پہنچ گئی تھی۔
ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنے کام سے فارغ ہوکر، اس گھر میں واپس نہیں گئی تھی۔ ابو امی پھوپھو رودیے تھے، چھوٹے بھائی بہن روہانسا تھے مگراپنی آپی کے درد کو سمجھ گئے تھے، مجھے پتا تھا کہ مار پیٹ کرنے والا شوہر کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ میرا فیصلہ اٹل تھا۔ میرے سسرال والوں نے بظاہر بڑی کوشش کی کہ میں واپس آجاؤں، شروع میں ابو کا بھی یہی خیال تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے۔ وہ کچھ پیسے جمع کر رہے تھے کہ اپنے داماد کو دیں گے، شاید سسرال والوں کا سلوک اچھا ہو جائے۔
مگر میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ طعن، تشنہ، طنز اور بے عزتی تو شاید میں برداشت کرلیتی، ماں باپ اور بہنوں کے لیے اندر اندرکڑھتی رہتی اورکچھ نہ کرتی لیکن مارپیٹ میرے برداشت سے باہر تھی۔ میں ڈاکٹر ہوکر اگر مار سہتی رہتی تو پھر مجھ میں اور اورنگی، کھوکھراپار، مچھرکالونی، چمڑا بستی، بنارس ٹاؤن کی اس لڑکی میں کیا فرق ہوتا جو تعلیم کی نعمت سے محروم تھی۔ میں نے ابو سے یہ بات نہیں کہی تھی لیکن انہیں جلد ہی سمجھ آ گئی تھی کہ میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا اٹل فیصلہ تھا۔
میں نے سعودی عرب میں نوکری کے لیے درخواست جمع کرائی تھی اور تقرری کے فوراً بعد اس چھوٹے سے شہر کے ہسپتال میں کام کرنے لگی تھی۔ بہت جلد میں نے ابو امی کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بکھرتی ہوئی دیکھی۔ مجھے پتا تھا کہ چند سالوں کی بات ہے سارے بھائی بہن تعلیم حاصل کر لیں گے تو بہت اچھا کمائیں گے، میں اپنی طرح کسی کی زندگی کوکٹھور نہیں بننے دوں گی۔ میری قسمت میں جو تھا وہ ہوگیا، دوسروں کی قسمت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی قسمت میں لکھوں گی، خریدوں گی، بدلوں گی۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیں گے تو میں بھی مزید پڑھوں گی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا پیشہ مجھے بہت کچھ دے گا۔ میں بہت دور تک جاؤں گی، آہستہ آہستہ میں اپنی شادی کے ڈراؤنے خواب کو بھول رہی تھی۔ میری تعلیم نے جیسے میرے راستے پر روشنیاں بھردی تھیں۔
اس کا نام سلاما ہاتکی تھا وہ جکارتہ سے چار سو میل دورایک چھوٹے سے شہر آئی تھی۔ اس کے سر پر زخم تھے مگر سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ بائیں ہاتھ کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں جنہیں پلاسٹر لگا کر ام موبی لائز کر دیا گیا تھا۔ دونوں پیر سلامت تھے، پیٹ کے اوپر زخم تھے لیکن اندرونی طور پر اعضاء محفوظ تھے۔ اسے وارڈ میں داخل کر لیا گیا، مجھے اندازہ تھا کہ اسے کچھ ہفتوں تک ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ اسے نیند کے انجکشن لگا کر سلادیا گیا تھا، مجھے اس سے ہمدردی ہوگئی تھی۔ دوسرے دن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر تکلیف عیاں تھی۔ وہ انگلش میں بات کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوگئے تھے۔
مجھے دوبارہ سے سب کچھ یاد آ گیا۔ سسرال والوں کے طنز بھرے الفاظ، چہروں پر خاموش نفرت، غصے سے بھرے ہوئے شوہر کے چہرے کے روپ اور وہ گھونسے، لات، تھپڑ جنہیں میں بہت دنوں تک سہتی رہی تھی۔ نہتی کمزور لڑکیوں پر تشدد کرنے والے مرد ہی اصل میں نامرد ہوتے ہیں۔ کاش اس نامردی کی بھی کوئی دوا ہوتی جو ان کے اندر کی اس نامردی کو مردانگی میں بدل دیتی لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس قسم کے نامردی خاندانی ہوتی ہے۔
میں نے بڑی لگن اور ہمدردی سے اس کا علاج کیا۔ وہ آہستہ آہستہ صحیح ہو رہی تھی اورمجھ سے شناسا بھی ہوگئی تھی۔ شروع کے کئی دن تو وہ آدھی جاگتی، آدھی سوتی اور روتی رہی تھی مگر جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہوئے اور درد کی شدت کم ہوئی، ویسے ویسے اس کے چہرے پر جیسے روشنی سی آتی جارہی تھی۔ بلاشبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے جسم کی ساخت سے پتا لگتا تھا کہ وہ ساری زندگی جسمانی محنت کرتی رہی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بڑی بڑی پررونق آنکھیں تھیں۔ جو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتی تھیں، میری ہمدردی میں شامل میرا اپنا دکھ اتنا شدید تھا کہ وہ مجھے نظرانداز نہیں کر سکتی تھی۔
ایک دن میں اسے دیکھنے ہی جارہی تھی تو پتا لگا کہ مقامی پولیس کے کارندے اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ دو تھے اور ان کے ساتھ ایک ترجمہ کرنے والا بھی تھا۔ وہ لوگ تقریباً چالیس منٹ تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد میں اس کے پاس پہنچی۔ اس کے چہرے پر شدید دکھ کا احساس تھا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ مسلسل روتی رہی ہے۔ میں نے اسے پانی دیا، اس کے زخموں کو صاف کیا، ان کی ڈریسنگ کی اور اس کے بستر کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔
”بڑے برے برے سوال کر رہے تھے وہ لوگ، ویری ڈرٹی۔ بہت برا۔“ اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے کہا۔
پھر آہستہ سے بولی کہ ”میں نے انہیں سب کچھ بتادیا ہے، سب کچھ، کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ انصاف تو ملنا مشکل ہے مگر میں تو صرف دعا ہی کر سکتی ہوں۔“ پھر آہستہ آہستہ زیرلب کچھ بڑبڑانے لگی۔ شاید کوئی دعا، شاید گھر واپس جانے کی التجا، اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔
میں نے پہلی دفعہ اس سے پوچھا کہ ”کیوں مارا تھا اسے اس کے مالک نے۔ اس بری طرح سے تو پاگل جانور کو بھی کوئی نہیں مارتا ہے۔ جانور بھی جانور پر اس قسم کا تشدد نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کیا جرم تھا تمہارا کہ تمہیں جان سے مارنے پر تلے ہوئے تھے وہ لوگ۔“
وہ دھیرے سے مسکرائی، پٹیوں اور پلاسٹروں کے باوجود اس کی آنکھوں میں سنگین قسم کی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ میں اس وقت اس مسکراہٹ کو کوئی معنی نہیں پہناسکی لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی شریر مسکراہٹ پر سنجیدگی طاری ہوگئی اور اس کا خوبصورت چہرہ دوبارہ سے اداسی میں کھوگیا، آنکھیں پھر جھلملا گئیں۔ میں بھی خاموش ہی رہی تھی۔
دو دن کے بعد جب میں اس کے بستر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی تو ایک سرکاری کارندے نے ایک بڑا سا لفافہ دیا۔ اس نے بتایا کہ سلاماہاتکی کا ورک پرمٹ واپس لے لیا گیا ہے اورپندرہ دن کے اندر اسے ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لفافے میں اس کے واپسی کا ٹکٹ، اس کے پاسپورٹ کے ساتھ تھا۔
سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں کام کرنے والے اپنے پاسپورٹ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ انہیں تنخواہ ضرور وافر مقدار میں دی جاتی ہے مگر اپنے ملک کو واپسی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے۔ معاشی غلامی بھی انسان کو کیسے کیسے روپ دے دیتی ہے۔ سلاماہاتکی کا نہ جانے کیا قصور تھا کہ اسے ملک چھوڑنے کا حکم مل گیا تھا۔ اس کا جو بھی کچھ سامان تھا وہ اس کے مالکوں کے قبضے میں تھا اور نہ ہی اسے اس کی تنخواہ دی گئی تھی اور نہ ہی اس پر ہونے والے ظلم کا کوئی مداوا تھا۔
اپنے اخراج کی خبر سن کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو ایسا لگا جیسے وہ اندر سے خوش ہو رہی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا کہ میں اس ٹکٹ پر اس کے جانے کی فلائٹ بک کردوں۔ وہ جلدازجلد سعودی عرب چھوڑکر انڈونیشیا واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے ہسپتال کے ہی ایک اہلکار کو اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ دیدیا، تاکہ وہ اس کی واپسی کا انتظام کردے۔
وہ اب چلنے پھرنے کے قابل ہوگئی تھی اورایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی۔ جانے سے پانچ دن قبل میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے ہمدردی ہوگئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ بقیہ دن وہ میرے ہسپتال کے فلیٹ میں گزارلے۔ گھر کے ماحول میں ہسپتال سے باہر، میری خواہش تھی کہ وہ تھوڑا نارمل سی ہو جائے۔
دوسرے دن میں گھر واپس آئی تو گھر میں ایک لذیذ قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زخم اور پلاسٹر کے باوجود سلاما نے میرے لیے انڈونیشی کھانے پکائے ہوئے تھے۔ وہ ایک اچھی شام تھی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کی کتاب کے کچھ صفحے کھول دیے تھے۔
”اس کے ماں باپ کسان تھے، غریب لوگ، سات بھائی بہنوں میں وہ سب سے بڑی تھی۔ اس کے سارے چھوٹے بھائی بہن کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے اوراسکولوں میں پڑھنے بھی جاتے تھے۔ وہ بھی اسکول سے فارغ ہوکر آگے پڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے باپ کا ٹریکٹر کے ایک حادثے میں انتقال ہوگیا۔ باپ کا کیا انتقال ہوا کہ ساری دنیا تلپٹ ہوکر رہ گئی، کسان کسی بھی ملک کا ہو وہ مرجائے تو اس کا خاندان مرے بغیر ہی مرجاتا ہے۔ ایسے میں اس نے سوچا کہ وہ دو تین سال کے لیے سعودی عرب میں آیا بن کر کام کرلے گی۔
انڈونیشیا سے بہت سی عورتیں سعودی عرب کام کرنے آتی ہیں۔ انڈونیشی مسلمانوں کے لیے سعودی عرب آنا ہی بڑا ثواب کا کام ہے پھر نوکری بھی ہو تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی تھی۔ سعودی بھی انڈونیشی مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں لہٰذا کام ملنا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک ایجنسی میں اس نے کاغذات جمع کرائے اور دو مہینے کی تنخواہ ان لوگوں نے لے کر اسے سعودی عرب کام پر بھیج دیا تھا۔
شروع شروع میں تو سب کچھ اچھا تھا، بھرا پرا گھر تھا، صبح سے شام تک میں کام کرتی، اچھے پیسے ملتے جو میں اپنی ماں کو انڈونیشیا بھیج دیتی تھی اور جلد ہی گھر والے سنبھل گئے تھے مگر آٹھ ماہ کے بعد جب شیخ کے سارے گھر والے اپنے گاؤں گئے تو وہ گھر میں اکیلی تھی اورپہلی رات ہی شیخ نے اسے اپنی خوابگاہ میں بلا کر زبردستی پامال کیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کرسکی اور جب تک گھر والے واپس نہیں آئے وہ اسے اس کی مرضی کے خلاف تقریباً روزانہ پامال کرتا رہا۔
پھر کچھ مہینوں کے بعد ایک دفعہ شیخ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے کہیں گیا تھا اور وہ پورا ہفتہ شیخ کا بڑا بیٹا اسے پامال کرتا رہا۔ میں چاہنے کے باوجود نہ کسی سے کہہ سکی، نہ شکایت کرسکی، نہ چیخ سکی اور نہ ہی جان چھڑا کر بھاگ سکی۔ اگر بھاگ بھی جاتی تو کیا ہوتامیرا سارا گھر بکھر جاتا۔ بھائی بہن اسکول سے نکل جاتے، میری ماں کیا کیا کرتی، گھر پھر اجڑ جاتا۔ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ جب بھی میں نے تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وہ میری پیٹھ اور پیٹ پر گھونسوں اور لاتوں سے وار کرتے، میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اسی طرح سے ان کے ہوس کا نشانہ بنتی رہوں۔
نہ جانے یہ کیسے ہوا کہ میں حمل سے نہیں ٹھہری جس کا خوف مجھے ہر وقت رہتا تھا۔ میرے دل میں ان باپ اوربیٹا دونوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہوگئی تھی۔ میں ان سے انتقام لینا چاہتی تھی مگر انتقام نہیں لے سکتی تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ”
یہ کہہ کر وہ خاموش ہوگئی۔ پھر دھیرے سے مسکرائی اوراس کی آنکھوں میں ایک چمک سے آ گئی۔
”میں نے بدلے کا اپنا ایک طریقہ نکال لیا تھا۔“ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ”میں نے ان دونوں کے قہوے میں اپنا پیشاب ملانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے پامال کرتے اور میں انہیں اپنا پیشاب پلاتی تھی۔ مجھے سکون سا ملتا تھا، نہ جانے کیوں ڈر ڈر کر میں روزانہ ان کے قہوے کے ذریعے انہیں اپنے پیشاب سے سیراب کرتی رہی۔ کئی مہینوں سے یہ ہورہا تھا، بس اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ انہیں پتا لگ گیا تھا کہ وہ میرا پیشاب پی رہے ہیں اور بہت دنوں سے پی رہے ہیں۔“
اس کے چہرے پر ایک طرح کی فاتحانہ شرارت بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔
”میرے زخم تو بھر جائیں گے مگر ان میں تھوڑی بھی غیرت ہوگی تو وہ ساری عمر الٹیاں کرتے رہیں گے، ساری عمر قہوہ نہیں پی سکیں گے۔“ اس کے چہرے پر جیسے اطمینان کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔
پہلی دفعہ اس کے لیے میرے اندر کی ہمدردی محبت میں بدل گئی تھی۔
- گھمنڈی - 05/01/2024
- تم جیو ہزاروں سال - 25/12/2023
- ایک انگوٹھی - 21/12/2023

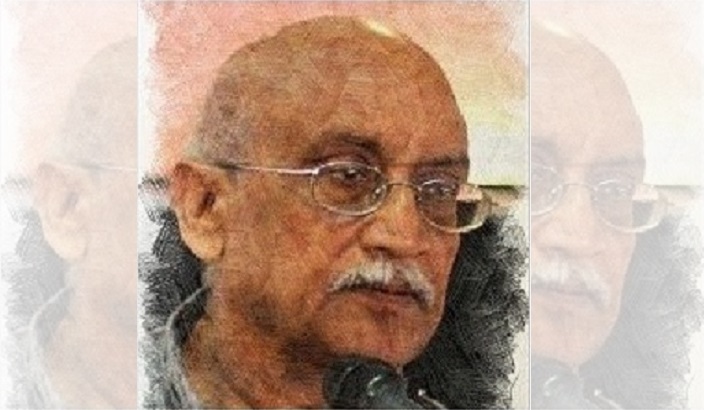

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).