عورت کا سرطان
”بچہ دانی کے منہ کا کینسر مسلمان اور یہودی عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے، پتا ہے کیوں؟“
میرے باس نے سوال کیا تھا اور میرے جواب سے پہلے وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ ”اس لئے کہ مسلمان اور یہودی دونوں ختنہ کراتے ہیں اور دونوں ہی مذہب کے ماننے والوں میں جنسی بے راہ روی کم ہے۔ تمہیں تو پتا ہے ناں کہ بچہ دانی کے منہ کا کینسر جو ان عورتوں کو ہوتا ہے۔ تیس سے پینتیس سال کی عورتوں کو۔ ان عورتوں کو جن کی جنسی زندگی تیرہ چودہ سال کی عمر سے ہی شروع ہوجاتی ہے۔ جن کے بہت سارے جنسی ساتھی ہوتے ہیں، جن کے جنسی ساتھیوں کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ابھی تک کا سائنسی علم یہی کہتا ہے۔“
رضیہ کے مرنے کی جتنی خوشی مجھے ہوئی اتنی شاید کسی کو بھی نہیں ہوئی ہوگی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے لئے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات پہلے ہوئی ہی نہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہو گا۔
باقی لوگوں کے لئے رضیہ محض ایک عورت تھی، ایک جواں سال عورت، قبول صورت عورت۔ ایک ایسی جو ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں موجود ہے، ہم سب کے دروازوں سے گزرتی ہوئی، ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ ہمارے گھروں کے کام کاج کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ وہ کبھی آتی ہے کبھی غائب ہوجاتی ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں، وہ پھر نمودار ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر خاموشی سے مر جاتی ہے اور لوگ باگ اس کے مرنے پر رسمی تعزیتی جملے کہتے ہیں۔ افسوس کرتے ہیں، ایک ایسا افسوس جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔
اگر آپ کو رضیہ کے بارے میں پتا ہو تو آپ بھی افسوس نہ کریں بلکہ خوش ہوں۔ ایسے ہی خوش جیسے میں ہوا تھا۔ اس کی موت خوشی منانے کے لئے ہی تھی۔
اسے ایدھی ایمبولینس کا ایک ڈرائیور جاوید میرے پاس لے کر آیا تھا۔ جاوید اچھا آدمی تھا، اچھا ڈرائیور تھا۔ وہ میرے ہسپتال میں ہمیشہ ایمرجنسی میں ہی مریض لے کر آتا تھا۔ حاملہ عورتیں جن کا خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ حاملہ عورتیں جنھیں دورے پڑ رہے ہوتے تھے، حاملہ عورتیں جو حمل ضائع کرانے کے دوران کسی مشکل کا شکار ہو گئی تھیں اور پھر ہمارے ہسپتال پہنچائی گئی تھیں۔ وہ اپنا کام بہت ہی ایمانداری سے کرتا تھا اور یقیناً بہت سی جانیں بچانے میں اس نے بہت کچھ اپنے پاس سے کھویا تھا۔
رضیہ اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے وہ ایک عام سی عورت لگی۔ کالا برقعہ پہنے ہوئے۔ ایک عجیب قسم کی سراسیمگی اور کشش تھی اس کے چہرے پر۔ برقعے نے اس کا جسم ڈھانپا ہوا تھا مگر چہرے پر کسی قسم کا کوئی نقاب نہیں تھا۔ وہ جاوید کے ساتھ خاموشی سے میرے کمرے میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔
تھوڑی دیر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی سراسیمگی اور کشش کے پیچھے ایک کم زوری تھی ایک درد تھا، کچھ تھا جو اس نے اپنے سینے کے اندر، بہت اندر اپنے دل کے کسی بہت ہی گہرے خانے میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔
جاوید نے بتایا تھا کہ رضیہ اس کے محلے میں ہی رہتی ہے۔ ایک جھگی سی ڈال رکھی ہے اس نے اپنے دو بچوں کے ساتھ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کہیں سے آئی تھی، شوہر کے مرنے کے بعد کوئی نہیں تھا اس کا اور اب بنگلوں میں جھاڑو پونچھے کا کام کر کے کسی نہ کسی طرح سے اپنا گھر اور کام چلا رہی ہے۔
میں نے جاوید سے باہر بیٹھنے کو کہا اور ڈاکٹر عذرا سے کہا کہ ذرا رضیہ کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟
رضیہ مسلسل خون بہنے کے سبب سے آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ چھ ماہ قبل اس کا شوہر مر گیا تھا جس کے بعد سے خون مسلسل بہہ رہا ہے، آہستہ آہستہ کر کے، وقت بے وقت۔ کبھی خود ہی رک جاتا تھا اور کبھی خود ہی بہنا شروع ہوجاتا ہے۔ پتا نہیں اسے کس قسم کی اندرونی بیماری ہو گئی تھی۔
میں نے جب اس کا معائنہ کیا تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ اسے بچہ دانی کے منھ کا کینسر ہے اور مرض بہت آگے تک جا چکا ہے، اس قابل نہیں تھا کہ آپریشن کر کے کینسر زدہ بچہ دانی کو نکالا جا سکے۔ مجھے معائنہ کرتے وقت بڑا افسوس ہوا تھا کہ یہ جوان عورت کچھ مہینوں میں آہستہ آہستہ، رک رک کر، تھکی تھکی موت کا شکار ہو جائے گی۔ مجھے اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے کہہ سکوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بچوں کا کیا ہو گا؟ شوہر پہلے ہی مر چکا ہے، میرے دھویں جیسے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی بھانپ گئی تھی کہ خبر اچھی نہیں ہے۔
میں نے جاوید کو بلایا تھا اور اس کے سامنے اسے سمجھایا کہ اسے بچہ دانی کے منھ کا کینسر ہو گیا ہے۔ اس کا علاج شروع میں تو یہ تھا کہ آپریشن کر کے بچہ دانی ہی نکال دی جائے مگر اب مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ آپریشن ممکن نہیں ہے۔ علاج کے لئے جناح ہسپتال جانا پڑے گا جہاں پر بجلی لگا کر علاج کیا جائے گا، مگر علاج کا کتنا فائدہ ہو گا اور مرض میں کتنا افاقہ ہو گا؟ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاسکتا۔
میں چاہنے کے باوجود اسے نہیں بتا سکا کہ اب موت اس کے دروازے پر کھڑی ہے اور یہ کہ جناح ہسپتال کی ریڈیو تھراپی بھی اس کی جان نہیں بچا سکے گی۔ وہ کینسر کے آخری اسٹیج پر ہے اور اب اس کی موت ہی اسے درد کے مستقل عذاب سے نجات دلا سکے گی۔
میں اکثر سوچتا ہوں زندگی اتنی ظالم، سفاک، اتنی بے پروا، اتنی بے غرض کیوں ہے؟ یکایک ختم ہوجاتی ہے، کچھ نہیں دیکھتی، کچھ نہیں سمجھتی۔ چھوٹے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں، ماتم کرتے ہوئے جوان مرد عورت، حالات، وقت کا تقاضا، یہ کچھ نہیں سوچتی۔ کچھ نہیں سمجھتی۔ مجھے کینسر کے مریض دیکھ کر ایک عجیب قسم کی بے بسی اور بے قراری سی ہوجاتی ہے۔ عجیب قسم کی اداسی کا شکار ہوجاتا ہوں اور اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ اس صبح کو بھی میں عادت کے مطابق اپنی پرانی کاپیوں میں سے پچھلے نوٹس پڑھ رہا تھا اور بچہ دانی کے منھ کے کینسر کے بارے میں اپنے بڈھے باس کی باتیں یاد کر رہا تھا کہ آج رضیہ یہ مرض لے کر آئی تھی۔ تمام تر خوف ناک مسائل کے ساتھ۔ جوان عورت، چھوٹے بچے غربت۔ موت۔ زندگی کسی کو تو سہارا دے۔ میں صرف سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔
میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی سراسیمگی شدید اور گہری ہوتی چلی گئی تھی۔
” تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟“ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔
میں نے بڑی ہمت کر کے جواب دیا تھا کہ ہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مگر کوششیں ضرور کریں گے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی ڈھول کی زبان میں بول رہا ہوں۔ تیز دھم دھم کر کے، مگر جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ جس کی آواز تو ہے مگر احساس سے خالی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کے ڈاکٹروں کے لئے موت بھی ایک عام واقعہ ہوتی ہے۔ وہ موت دیکھ دیکھ کر موت کے ایک طرح عادی سے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں احساس ختم ہوجاتا ہے۔ یہ تجربہ انھیں سنگ دل اور بدتمیز بنا دیتا ہے پھر وہ موت کے بارے میں باتیں کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اور میں نے دیکھا بھی تھا، زیادہ تر کینسر کے ماہر ڈاکٹر مریضوں سے بڑھ کر درشتگی سے بات کرتے ہیں۔ شاید مریض کا مرنا مریض کے رشتے داروں کے لئے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کینسر کے ڈاکٹر کا درشت رویہ اور بھیانک چہرہ اذیت ناک ہوتا ہے جو موت کی خبر سناتا ہے بے رحمی کے ساتھ۔
میں نے جناح ہسپتال کے ڈاکٹر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا کہ جاوید اسے وہاں لے جائے تاکہ اس کا جو علاج بھی ممکن ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے۔
دو ہفتے بعد جب میں رضیہ کو دوسرے مریضوں کے ہجوم میں کھو کر بھول چکا تھا، وہ صبح صبح میرے کمرے میں آئی تھی، اس کے چہرے پر نقاہت تھی اور ستا ہوا چہرہ کم زوری کے باوجود خوب صورت لگ رہا تھا۔
میں نے اس سے بہت ہمدردی سے بات کی۔ وہ بہت پریشان تھی، مجھے اندازہ تھا کہ موت کا خدشہ کتنا پریشان کن ہوتا ہے۔ ایسا زہر ہے جو بہت ٹھہر ٹھہر کر اور دھیرے دھیرے جان لیتا ہے۔ ذہن اور روح دونوں کو کچلتا رہتا ہے۔
”ڈاکٹر میں کتنے دن اور بچوں گی؟“ اس نے بڑی التجا سے سوال کیا تھا۔ ”مجھے ایک دفعہ بجلی لگائی گئی ہے مگر میں تو بہت کم زور ہو گئی ہوں، میرے بچوں کا کیا ہو گا، ڈاکٹر مجھے صاف صاف بتا دو، کچھ چھپانا مت مجھ سے۔“
آخری جملے نے مجھے بھی حوصلہ دیا تھا کہ صاف صاف سچ اسے بتا دوں۔ اور میں نے یہی کیا تھا۔
میں اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ہسپتال کی آیا میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے کہا تھا کہ چھ آٹھ ماہ سے زیادہ وہ نہیں بچ سکے گی اور موت کے آخری دن بڑی مشکلات والے ہوں گے، درد ہو گا اور تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ ”میں تمہاری مدد کروں گا، ہسپتال میں داخل کر لیں گے تم کو۔ تم نے بڑی بہادری دکھائی ہے۔ بہت بہادری سے سوال کیا ہے اور بہادری سے ہی سب کچھ سہنا ہو گا۔ دیکھو موت تو اٹل ہے وہ آہی جاتی ہے اور یہ سب کچھ سہنا ہی ہوتا ہے۔“ بہت مشکل سے یہ سب کچھ میں نے کہا تھا بہ ظاہر سیدھے سادے الفاظ میں لیکن وہ کتنے مشکل ہوں گے اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔
اس نے بڑی زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ”میں موت سے نہیں ڈرتی ہوں جو زندگی میری ہے اس کے بعد تو موت بھی اچھی ہوگی۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ مجھے بچوں کی فکر ہے ان کا کیا ہو گا؟“ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ خلا میں کچھ گھور رہی ہے۔ جیسے دور کہیں چھوٹا سا تارہ ٹمٹما رہا ہے۔ اسے بلا رہا ہے۔
مزید پڑھنے کے لیے اگلا صفحہ کا بٹن دبائیں
- گھمنڈی - 05/01/2024
- تم جیو ہزاروں سال - 25/12/2023
- ایک انگوٹھی - 21/12/2023

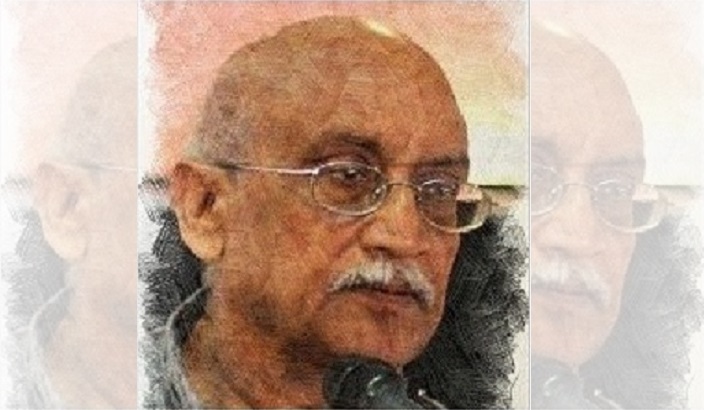

Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).