کیا پاکستانی عدالتیں اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتی ہیں؟

عدلیہ کو مقنّنہ اور انتظامیہ کے ساتھ ریاست کے بنیادی ستونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ عدلیہ کے بغیر ریاست کے وجود پر ہی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے اس لیے جس طرح مقنّنہ اور انتظامیہ کی کارکردگی ریاست کی مضبوطی پر اثرانداز ہوتی ہے اسی طرح عدلیہ کا کام بھی کسی طور نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا تھا ”تاریخ عالم کی سب سے بڑی نا انصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔“ برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم سرخرو ہوں گے۔
ایک انگریزی مقولے کے مطابق ”انصاف میں جلدبازی انصاف کو دفن کرنے کے مترادف ہے“ دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا ہے ”انصاف میں تاخیر کا مطلب انصاف سے انکار ہے“ ۔ ریاست اور معاشرے میں عدل کی اس اہمیت کو ہمارے ہاں بھی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عملاً ہم ابھی اس منزل سے بہت دور ہیں جہاں انصاف ہر شہری کی دسترس میں ہوتا ہے اور ایوانوں کے فیصلے اعتبار کا حصار لیے ہوتے ہیں۔
انسانی بنیادی حقوق سے متعلق کیسز ہوں یا پھر ایسے معاشرتی مسائل جن کا کوئی فوری حل نظر نہ آئے۔ ایسے میں پاکستان کے عوام عمومی طور پر عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ بعض معاملات میں عدالتی احکامات کی روشنی میں ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ بحث ہمیشہ جاری رہی ہے کہ کیا عدالتیں اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتی ہیں؟ اس ضمن میں عدالت جب کسی معاملے کا ازخود نوٹس لیتی ہے تو یہ معاملہ موضوع بحث بن جاتا ہے۔ یہاں یہ سوالات بہت اہم ہیں کہ جوڈیشل ایکٹوازم کی تعریف کیا ہے؟
قانونی ماہر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیو ازم نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بس ایک اصطلاح ہے۔ جو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب عدالت کسی ایسے مسئلے کو اٹھاتی ہے جس کی نوعیت فوجداری ہو نہ ہی دیوانی بلکہ اس کا براہِ راست تعلق بنیادی انسانی حقوق سے ہو۔ بنیادی انسانی حقوق میں صاف پانی کی دستیابی سے لے کر اسپتالوں میں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی جیسے مسائل شامل ہیں مگر وہ لکیر جو عدالتوں کو مقننہ اور انتظامیہ کے دائرہ کار سے علیحدہ کرتی ہے وہ بہت باریک ہے۔
سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ایک دو کام تو عدالتی احکامات کی روشنی میں ہو جاتے ہیں لیکن ایکٹوازم کے نتیجے میں کوئی دیرپا تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایسی تبدیلیاں سیاسی اور انتظامی ادارے ہی لا سکتے ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجیسلیٹو ڈویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپرنسی (پلڈاٹ) کے صدر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ عدالتی دائرہ کار کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم اس کا تعین کیا جانا چاہیے ورنہ معاملات الجھ سکتے ہیں اور ماضی میں الجھتے بھی رہے ہیں۔
اُن کا کہنا ہے کہ عدالتیں ایسے مسائل پر بات کرتی ہیں جن پر ان کی معلومات بسا اوقات محدود ہوتی ہے لہذٰا اس کی روشنی میں دیے گئے احکامات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بہت سے فیصلے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے اسٹیل مل کی نجکاری روکی جبکہ ایل پی جی کے معاہدے کو بھی معطل کیا۔ لاہور کی اورنج لائن ٹرین کا معاملہ 22 ماہ تک عدالت میں رہا جس سے لامحالہ اس عوامی منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہوئی اور کئی مسائل پیدا ہوئے۔
احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹوازم کا راستہ خود سول حکومتوں نے کھولا ہے۔ ملک میں جمہوری قوتوں کو جان بوجھ کر کمزور رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے عدلیہ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل حنا جیلانی کہتی ہیں کہ جوڈیشل ایکٹوازم اس صورت میں لاگو ہوتا ہے جب انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا اندیشہ لاحق ہو۔ جب انتظامی یا دیگر ادارے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری نہ کریں اور اس سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہوں تو عدالتیں ان معاملات میں مداخلت کر کے ریلیف دے سکتی ہیں البتہ حنا جیلانی کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل ایکٹوازم کے باعث بعض انتظامی ادارے کمزور بھی ہوئے۔ حنا جیلانی کہتی ہیں کہ یہ منطق بالکل غلط ہے کہ چونکہ ایک آئینی ادارہ کمزور ہے تو اس کے دائرہ کار کی نفی کی جائے۔ ان کے بقول ”ہونا یہ چاہیے کہ اگر پارلیمان کمزور ہے تو ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے پارلیمان کو تقویت ملے، نہ کہ ایسے جس سے اس کی توقیر کم ہو جائے۔“
ہمارے ملک میں ان دنوں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور ہونی چاہیے؟ کیا جج متنازعہ کمنٹس کر سکتے ہیں؟ دنیا کے تمام مہذب ممالک میں یہ حق مانا گیا ہے بالخصوص قانون پڑھانے والوں اور قانونی ماہرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقدمات کے فیصلوں پر تفصیلی تنقید کریں اور ان کی اچھی اور بری باتوں کا جائزہ لیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے مشہور جج جسٹس اولیور ہومز نے امریکی سپریم کورٹ کے ایک مشہور فیصلے میں اختلافی نوٹ میں ایک بڑا دل چسپ جملہ لکھا کہ مشکل مقدمات کی طرح بڑے کیسز کے نتیجے میں جو قانون سامنے آتا ہے وہ بہت بُرا ہوتا ہے۔
بڑے کیسز سے مراد وہ جن میں ججز پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے جو میڈیا پر بہت زیادہ نمایاں ہوئے ہیں جن سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں جب ان کیسز کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہومز کے بقول وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہارورڈ کے ایک پروفیسر کی کتاب کا عنوان یہی ہے کہ بڑے مقدمات برے قانون کو جنم دیتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے امریکا کے چوبیس بڑے بڑے کیسز کو جمع کر کے تجزیہ کیا کہ ان کے نتیجے میں جو قانون بنے وہ صحیح تھے یا غلط۔
دراصل ترقی یافتہ ممالک میں انہی تجزیوں اور تبصروں کے نتیجے میں قانون آگے بڑھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر میں ججز کسی کیس کی شنوائی کے دوران متنازع ریمارکس تو دے دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ پریکٹس کچھ زیادہ ہی ہے۔ ججز کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کریں۔ کیس کی شنوائی کے دوران سوالات پوچھنے چاہئیں لیکن متنازع ریمارکس سے پرہیز بہتر ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جج فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں تو اُن کے ذہن میں یقیناً برطانوی نظام کا جج ہوتا ہے جو خاموش بیٹھتا ہے دراصل وہ ایڈورسرئیل سسٹم کا جج ہوتا ہے، اسے صرف فریقین کو دیکھنا ہے اور ان کی باتوں کو سننا اور نوٹ کرنا ہے اور پھر فیصلے کے ذریعے بولنا ہے لیکن جہاں جج انکوئزیٹوریل پاور رکھتا ہے وہاں جج بولتا ہے حتیٰ کہ ہمارے قانون شہادت میں جج کے سوال کرنے کا اختیار بھی موجود ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج بالخصوص دستوری معاملات میں زیادہ سے زیادہ سوالات کر سکتے ہیں لیکن ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کا تقاضا ہے کہ تماشائیوں اور میڈیا کو خوش کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ بد قسمتی سے یہ سلسلہ پچھلے دس پندرہ سال کے دوران چل پڑا ہے اور ماضی میں بعض ججز محسوس کرتے تھے کہ انہیں بھی عوام کو مخاطب کرنا چاہیے جبکہ اُصولی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔
- پاکستان کے طاقت ور اداروں کا ماضی - 25/05/2024
- کیا پاکستانی عدالتیں اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتی ہیں؟ - 23/05/2024
- اگرچہ نئے پاکستان کا سفر بہت لمبا ہے مگر قافلہ جانب منزل ہے - 09/04/2024

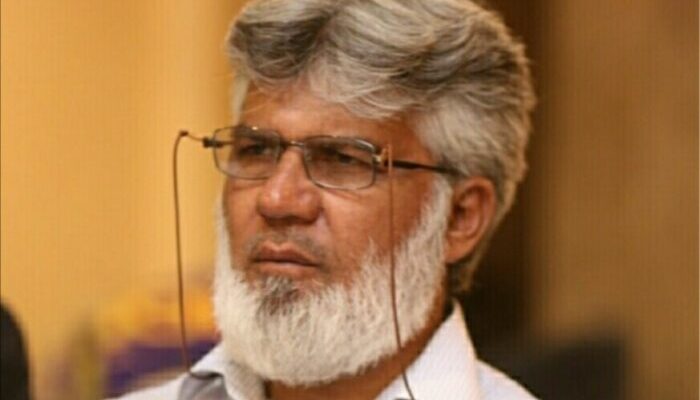
Facebook Comments - Accept Cookies to Enable FB Comments (See Footer).